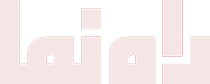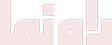یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ اور طویل رات کی بات ہے۔ میں اپنے گرم گرم بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سورہا تھا کہ کسی نے زور سے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔
”کون ہے۔“ میں نے چیخ کر پوچھا اور اس کے جواب میں ایک بڑا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گھپ اندھیرے سے آواز آئی: ”تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کرلیا۔“
”کیا؟“ میں لرزتے ہوئے ہاتھ کو پرے دھکیلنا چاہا۔ ”کیا ہے؟“
اور تاریکی کا بھوت بولا: ” تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کرلیا…. اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔“
”داؤ جی کے بچے“ میں نے اونگھتے ہوئے کہا۔ ”آدھی آدھی رات کو تنگ کرتے ہو…. دفع ہوجاؤ…. میں نہیں…. میں نہیں…. آپ کے گھر رہتا۔ میں نہیں پڑھتا…. داؤ جی کے بچے…. کتے!“ اور میں رونے لگا۔
داؤ جی نے چمکار کرکہا: ”اگر پڑھے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا! پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدمی نہ بن سکے گا، پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟“
”اللہ کرے سب مرجائیں۔ آپ بھی، آپ کو جاننے والے بھی…. اور میں بھی …. میں بھی….“
اپنی جوانمرگی پر ایسا رویا کہ دو ہی لمحوں میں گھگھی بندھ گئی۔
داؤ جی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے: ”بس اب چپ کر شاباش…. میرا اچھا بیٹا۔ اس وقت یہ ترجمہ کردے، پھر نہیں جگاؤں گا۔“
آنسوؤں کا تار ٹوٹتا جا رہاتھا۔ میں نے جل کر کہا: ”آج حرامزادے رانو کو پکڑ کر لے گئے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے۔ آپ کا ترجمہ تو….“
”نہیں نہیں۔“ انہوں نے بات کاٹ کر کہا۔ ”میرا تیرا وعدہ رہا آج کے بعد رات کو جگاکر کچھ نہ پوچھوں گا…. شاباش اب بتا۔ ”تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کرلیا۔“ میں نے روٹھ کر کہا۔ ”مجھے نہیں آتا“۔
”فوراً نہیں کہہ دیتا ہے۔“ انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ”کوشش تو کرو۔“ ”نہیں کرتا!“ میں نے جل کر جواب دیا۔
اس پر وہ ذرا ہنسے اور بولے: ”کارکنانِ گزمہ خانہ رانو را توقیف کردند…. کارکنانِ گزمہ خانہ، تھانے والے۔ بھولنا نہیں نیا لفظ ہے۔ نئی ترکیب ہے، دس مرتبہ کہو۔“
مجھے پتا تھا کہ یہ بلا ٹلنے والی نہیں، نا چار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑہ شروع کردیا۔ جب دس مرتبہ کہہ چکا تو داؤ جی نے بڑی لجاجت سے کہا اب سارا فقرہ پانچ بار کہو۔ جب پنجگانہ مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بسترمیں لٹاتے ہوئے اور رضائی اوڑھاتے ہوئے کہا: ”بھولنا نہیں! صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا۔“ پھر وہ جدھر سے آئے تھے، ادھر لوٹ گئے۔
شام کو جب میں ملاجی سے سیپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراسیوں والی گلی سے ہوکر اپنے گھر جایا کرتا۔ اس گلی میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے۔ مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا جس کو ہم سب ”کدو کریلا ڈھائی آنے“ کہتے تھے۔
ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑہ تھا جس کے تین طرف کچے پکے مکانوں کی دیواریں اور سامنے آڑی ترچھی لکڑیوں اور خار دار جھاڑیوں کا اونچا اونچا جنگلا تھا۔ اس کے بعد ایک چوکور میدان آتا تھا، پھر لنگڑے کمہار کی کوٹھڑی اور اس کے ساتھ گیرو رنگی کھڑکیوں اور پیتل کی کیلوں والے دروازوں کا ایک چھوٹا سا پکا مکان۔ اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہوجاتی۔ پھر جوں جوں اس کی لمبائی بڑھتی توں توں اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے۔ شاید وہ ہمارے قصبے کی سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان! اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہاہوں اور جونہی میں اس کے دہانے سے باہر نکلوں گا، زور سے ”ٹھائیں“ ہوگا اور میں مرجاؤں گا۔ مگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی راہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی۔
ان آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید سی مونچھوں والا لمبا سا آدمی ہوتا جس کی شکل بارہ ماہ والے ملکھی سے بہت ملتی تھی۔ سر پرململ کی بڑی سی پگڑی۔ ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ۔ کھدر کا تنگ پائجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ۔ اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا جس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے اور وہ آدمی سر جھکائے اور اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ میرے برابر آتے تولڑکا میری طرف دیکھتا تھا اور میں اس کی طرف اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹھکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا موڑتے ہم اپنی اپنی راہ پر چلتے جاتے۔
ایک دن میں اور میرا بھائی ٹھٹھیاں کے جوہڑ سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبہ کو واپس آرہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا اور اس کی سفید چٹیا میری مرغی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے سلام کیا: ”داؤ جی سلام“ اور داؤ جی نے سر ہلاکر جواب دیا: ”جیتے رہو“۔
یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے میں بے حد خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد اپنی منمنی آواز میں چلایا: ”داؤ جی سلام“۔
”جیتے رہو۔ جیتے رہو!!“ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پٹاخ سے میرے زناٹے کا ایک تھپڑ دیا۔
”شیخی خورے، کتے“ وہ چیخا۔ جب میں نے سلام کردیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمینہ…. بھلا کون ہے وہ؟“
”داؤ جی“ میں نے بسور کر کہا۔
”کون داؤ جی؟“ میرے بھائی نے تنک کر پوچھا۔
”وہ جو بیٹھے ہیں“ میں نے آنسو پی کر کہا۔
”بکواس نہ کر“ میرا بھائی چڑ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا: ”ہر بات میں میری نقل کرتا ہے کتا…. شیخی خورا۔“
میں نہیں بولا اور اپنی خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہوگیا۔ اس کا رنج نہ تھا کہ بھائی نے میرے تھپڑ کیوں مارا۔ وہ تو اس کی عادت تھی۔ بڑا تھا نا اس لیے ہر بات میں اپنی شیخی بگھارتا تھا۔
داؤ جی سے علیک سلیک تو ہو ہی گئی تھی، اس لیے میں کوشش کرکے گلی میں سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آجارہے ہوں۔ انہیں سلام کرکے بڑا مزا آتا تھا اور جواب پاکر اس سے بھی زیادہ۔ وہ ”جیتے رہو“ کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی دو چند سی ہو جاتی اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا….
سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال بھر یونہی چلتا رہا اور اس اثناء میں مجھے اس قدر معلوم ہوسکا کہ داؤ جی گیرو رنگی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا سا لڑکاان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اورمیری چھوٹی بات پر چڑ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں ا س کے پاس گھڑے گھڑائے دو فقرے ہوتے تھے: ”تجھے کیا“ اور ”بکواس نہ کر“ مگر خدا کاشکر ہے میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ اسلامیہ پرا ئمری سکول سے چوتھی پاس کرکے میں ایم۔ بی ہائی سکول کی پانچویں جماعت میں داخل ہوا تو وہی داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اُٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کھتری تھے اور قصبہ کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام ”امی چند“ تھا اور وہ جماعت میں سب سے زیادہ ہشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس بھر میں سب سے بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کے اصلی نام ہی سے پکارتا تھا۔ اس لیے وہ میرا دوست بن گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بننے کا وعدہ کرلیا تھا۔
گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی ایک ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر سکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔
امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور روشن۔ پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑھی تھی۔ آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ۔ عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑھی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر ”بے بے نمستے!“ کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریا بچھائے بے بے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی قینچی سے کپڑے قطع کررہی تھی۔ بے بے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھاکر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا: ”بے بے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔“
مشین رک گئی۔
”ہاں ہاں“ بے بے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے جز دان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آلگا۔
”کیا نام ہے تمہارا؟“ بے بے نے چمکارکر پوچھا اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتادیا۔
”آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے۔“ اس لڑکی نے قینچی زمین پر رکھ کر کہا۔ ”ہے نا بے بے؟“
”کیوں نہیں بھائی جو ہوا۔“
”آفتاب کیا؟“ اندر سے آوازآئی۔ ”آفتاب کیا بیٹا؟“
”آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی۔“ لڑکی نے رکتے ہوئے کہا۔ ”امی چند کے ساتھ آیا ہے۔“
اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پائجامہ چڑھا رکھا اور کرتہ اتارا ہوا تھا۔ مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آگئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے: ”ہاں بہت شکل ملتی ہے مگر میرا آفتاب بہت دبلا ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔“ پھر بالٹی فرش پر رکھ کے انہوں نے میرے سر ہاتھ پھیرا اور پاس کاٹھ کا ایک اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اٹھاکر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیا۔
”آفتاب کا خط آتا ہے؟“ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔
”آتا ہے جی۔“ میں نے ہولے سے کہا۔ ”پرسوں آیا تھا“۔
”کیا لکھتا ہے؟“
”پتا نہیں جی، ابا جی کو پتا ہے۔“
”اچھا۔“ انہوں نے سر ہلاکر کہا۔ ”تو ابا جی سے پوچھا کر نا! …. جو پوچھتا نہیں اسے کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا۔“
میں چپ رہا۔
تھوڑی دیر بعد انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا: ”کونسا سیپارہ پڑھ رہے ہو؟“
”چوتھا۔“ میں نے وثوق سے جواب دیا۔
”کیا نام ہے تیسرے سیپارے کا؟“ انہوں نے پوچھا۔
”جی نہیں پتا۔ ”میری آواز پھر ڈوب گئی۔
”تلک الرسل۔“ انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بے بے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کو کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ ساتھ جھینپ کی عمیق گہرائیوں میں اترتا جارہا تھا۔ معاً داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا….
”سورہ فاتحہ سناؤ۔“
”مجھے نہیں آتی جی۔“ میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔
انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا ”الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟“
”الحمدللہ تو میں جانتاہوں جی۔“ میں نے جلدی سے کہا۔
وہ ذرا مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے: ”ایک ہی بات ہے! ایک ہی بات ہے!!“ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پائجامہ گھٹنوں سے نیچے کرلیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کرکے کندھوں پر ڈال دیا اور جب میں نے ”وَلَا الضَّالِّیْنَ“ کہا تو میر ے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کہا تھا اور ساتھ ہی ایک روپیہ مجھے انعام بھی دیاتھا۔ مگرداؤ جی اسی طرح بیٹھے رہے بلکہ اور بھی پتھر ہوگئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کرکے لے آیا اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا: ”داؤ جی سلام“ اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا: ”جیتے رہو“۔
بے بے نے مشین روک کر کہا: ”کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آجایا کرو۔“
”ہاں ہاں آجایا کر۔“ داؤ جی چونک کر بولے۔ ”آفتاب بھی آیا کرتا تھا“ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا: ” ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہوگیا۔۔۔“ اور فارسی کا شعر سا پڑھنے لگے۔
یہ داؤ جی سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذکر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں۔ حد سے زیادہ چپ ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کویاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے کہا: ”تو مجھ سے پوچھ تو لیتا۔ بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے مگر تیرے اباجی ان سے بولتے نہیں ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہوگیا تھا سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ تو ان کے ہاں گیا تھا تو وہ خفا ہوں گے۔“ پھر اماں نے ہمدرد بن کر کہا: ”اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔“
میں ابا جی سے بھلا اس کاذکر کیوں کرتا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا۔
وہ چٹائی بچھائے کوئی کتا ب پڑھ رہے ہوتے۔ میں آہستہ سے ان کے پیچھے جاکر کھڑا ہوجاتا اور وہ کتاب بند کرکے کہتے: ”گولو آگیا۔“ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے: ”کوئی گپ سنا“ اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے۔ بس یونہی میرے لیے ہنستے حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے لے ایک سوال نکال۔ اس سے میری جان جاتی تھی لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا تھا کہ ایک سوال اور پندرہ منٹ باتیں۔ اس کے بعد ایک اورسوال اور پھر پندرہ منٹ گپیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔
اگر خوش قسمتی سے سوال جلد حل ہوجاتا تو وہ چٹائی کو ہاتھ لگاکر پوچھتے یہ کیا ہے؟ ”چٹائی۔“ میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا۔ ”اوں ہوں“ وہ سر ہلاکر کہتے۔ ”فارسی میں بتاؤ“ تو میں تنک کر جواب دیتا: ”لو جی ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے۔“ اس پر وہ چمکار کر کہتے: ”میں جو پڑھاتا ہوں گولو…. میں جو سکھاتا ہوں…. سنو! فارسی میں بوریا، عربی میں حصیر“ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا: ”بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی، میں نہیں پڑھتا مجھے معاف کرو“ مگر وہ سنی ان سنی ایک کرکے کہے جاتے فارسی بوریا، عربی حصیر۔ اور پھر کوئی چاہے اپنے کانوں میں سیسہ بھر لیتا۔ داؤ جی کے الفاظ گھستے چلے جاتے تھے….
امی چند کتابوں کا کیڑا تھا۔ سارا دن بیٹھک میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے داؤ امی چند پر بھی برابر ہوتے تھے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھڑے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا۔ ”بیٹا؟؟؟؟“۔ ”کیا ہے؟“ اس نے گلاس کے ساتھ منہ لگائے لگائے ”ڈیڈ“ کہا اور پھر گلاس گھڑونچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آگیا۔ داؤ جی پھر پڑھنے میں مصروف ہوگئے۔
گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام قرۃ رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہانک لگا کر کہتے ”قرۃ بیٹی یہ قینچی تجھ سے کب چھوٹے گی؟“ اور وہ اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہوجاتی۔
بے بے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چیخ کر جواب دیتی: ”تم نے اس کانام قرۃ رکھ کر اس کے بھاگ میں کرتے سینے لکھوا دئیے ہیں۔ منہ اچھا نہ ہوتو شبد تو اچھے نکالنے چاہئیں“ اور داؤ جی ایک لمبی سانس لے کر کہتے: ”جاہل اس کا مطلب کیا جانیں۔“ اس پر بے بے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو کچھ آتا کہتی چلی جاتی۔ پہلے کوسنے، پھر بددعائیں اور آخر میں گالیوں پر اتر آتی۔ بی بی رکتی تو داؤ جی کہتے: ”ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا، اور گالیاں برسنے کو، تم انہیں روکو مت، انہیں ٹوکو مت۔“
پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنا محبوب حصیر اٹھاکر چپکے سے سیڑھیوں پر چڑھ جاتے۔
نویں جماعت کے شروع میں مجھے ایک بری عادت پڑگئی اور اس بری عادت نے عجیب گل ککھلائے۔ حکیم علی احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے۔ علاج معالجہ سے ان کو کچھ ایسی دلچسپی نہ تھی لیکن باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے۔ اولیاؤں کے تذکرے، جنوں بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمانؑ اور ملکہ سبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیر بہدف ٹوٹکے تھے۔ ان کے تنگ و تاریک مطب میں معجون کے چند ڈبوں، شربت کی دس پندرہ بوتلوں اور دو آتشی شیشیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دواؤں کے علاوہ وہ اپنی طلسماتی تقریر اور حضرت سلیمانؑ کے خاص صدری تعویذوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھنچے چلے آتے اور فیض یاب ہوکر جاتے۔ ہفتہ دو ہفتہ کی صحبت میں میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوگیا۔ میں اپنے ہسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں چرا کے لاتا اور اس کے بدلے وہ مجھے داستانِ امیر حمزہ کی جلدیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے۔
یہ کتابیں کچھ ایسی دلچسپ تھیں کہ میں رات رات بھر اپنے بسترمیں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ اماں میرے اس رویے سے سخت نالاں تھیں۔ ابا جی کو میری صحت برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا لیکن میں نے ان کو بتادیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے اب کے دسویں میں وظیفہ ضرور حاصل کروں گا۔ رات طلسم ہوشربا کے ایوانوں میں بسر ہوتی اور دن بینچ پر کھڑے ہوکر۔ سہ ماہی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچا۔ ششماہی میں بیمار پڑ گیا اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم جی کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا۔
دسویں میں صندلی نامہ، فسانۂ آزاد اور الف لیلیٰ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ فسانۂ آزاد اور صندلی نامہ گھر پر رکھے تھے، لیکن الف لیلیٰ سکول کے ڈیسک میں بند رہتی۔ آخری بینچ پر جغرافیہ کی کتاب تلے سند باد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا….
بائیس مئی کا واقعہ ہے کہ صبح دس بجے یونیورسٹی سے نتیجہ کی کتاب ایم۔ بی ہائی سکول پہنچی۔ امی چند نہ صرف سکول میں بلکہ ضلع بھر میں اول آیا تھا۔ چھ لڑکے فیل تھے اور بائیس پاس۔ حکیم جی کا جادویونیورسٹی پر نہ چل سکا اور پنجاب کی جابر دانش گاہ نے میرا نام بھی ان چھ لڑکوں میں شامل کردیا۔ اسی شام قبلہ گاہی نے بید سے میری پٹائی کی اورگھر سے باہر نکال دیا۔ میں ہسپتال کے رہٹ کی گدی پر آبیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور اب کدھر جانا چاہیے۔
خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمرو عیار کے ہتھکنڈوں اور سند باد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا مگر پھربھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ کوئی دو تین گھنٹے اسی طرح ساکت وجامد اس گدی پر بیٹھا زیست کرنے کی راہیں سوچتا رہا۔ اتنے میں اماں سفید چادر اوڑھے مجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی ادھر آگئیں اور اباجی سے معافی لے دینے کا وعدہ کر کے مجھے پھر گھر لے گئیں۔ مجھے معافی وافی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے تو بس ایک رات ا ور ان کے یہاں گزارنی تھی اور صبح سویرے اپنے سفرپر روانہ ہونا تھا، چنانچہ میں آرام سے ان کے ساتھ جا کر حسب معمول اپنے بستر پر دراز ہوگیا۔
اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا کوڈو اور دیسو یب یب مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پاس بیٹھے مل گئے۔ وہ لاہورجاکر بزنس کرنے کا پرو گرام بنا رہے تھے۔ دیسو یب یب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بڑا بزنس ہے کیونکہ اس کے بھایا جی اکثر اپنے دوست فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے جس نے سال کے اندراندر دو کاریں خرید لی تھیں۔ میں نے ان سے بزنس کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تو یب یب نے کہا لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے۔ بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سا سائن بورڈ۔ سائن بورڈ دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں۔ اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی نوٹ لے رہا تھا۔
میں نے ایک مرتبہ پھر وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا: ”یار دیسو سب جانتا ہے۔ یہ بتا، تو تیار ہے یا نہیں؟“
پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا: ”انار کلی میں دفتر بنائیں گے نا؟“
دیسو نے ذرا سوچ کر کہا: ”انار کلی میں یا شاہ عالمی کے باہر دونوں ہی جگہیں ایک سی ہیں۔“
میں نے کہا: ”انار کلی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہی زیادہ مشہور جگہ ہے اور اخباروں میں جتنے بھی اشتہار نکلتے ہیں ان میں انار کلی لاہور لکھا ہوتا ہے۔“
چنانچہ یہ طے پایا کہ اگلے دن دو بجے کی گاڑی سے ہم لاہور روانہ ہوجائیں!
گھر پہنچ کر میں سفرکی تیاری کر نے لگا۔ بوٹ پالش کررہا تھا کہ نوکر نے آکر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا: ”چلو جی ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔“
”کہاں ہیں؟“ میں نے برش زمین پر رکھ دیا اور کھڑا ہوگیا۔
”ہسپتال میں “ وہ بدستور مسکرا رہا تھا کیونکہ میری پٹائی کے روز حاضرین میں وہ بھی شامل تھا۔
میں ڈرتے ڈرتے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا۔ پھر آہستہ سے جالی والا دروازہ کھول کر اباجی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہا ں ان کے علاوہ داؤ جی بھی بیٹھے تھے۔ میں نے سہمے سہمے داؤ جی کو سلام کیا اور اس کے جواب میں بڑی دیر کے بعد جیتے رہو کی مانوس دعا سنی۔
”ان کو پہچانتے ہو؟“ اباجی نے سختی سے پوچھا۔
”بے شک۔“ میں نے ایک مہذب سیلزمین کی طرح کہا۔
”بے شک کے بچے، حرامزادے، میں تیری یہ سب….“۔
”نہ نہ ڈاکٹرصاحب“ داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھاکر کہا۔ ”یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے اس کو تو ….“
اور ڈاکٹرصاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا: ”آپ نہیں جانتے منشی جی اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملادی۔“
”اب فکر نہ کریں۔“ داؤ جی نے سر جھکائے کہا۔ ”یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے اور ایک دن….“
اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آگیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مارکر کہا: ”کیسی بات کرتے ہو منشی جی! یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کرسکتا۔“
”کرے گا، کرے گا…. ڈاکٹر صاحب“ داؤ جی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا: ”آپ خاطر جمع رکھیں۔“
پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے: ”میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔“
اباجی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے اور بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داؤ جی نے پیچھے مڑ کر کہا:
”ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے ابھی بھجوا دیجیے گا۔“
داؤ جی مجھے ادھر ادھر گھماتے اور مختلف درختوں کے نام فارسی میں بتاتے نہر کے اسی پل پر لے گئے جہاں پہلے پہل میرا ان سے تعارف ہوا تھا۔ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کر انہوں نے پگڑی اتار کرگود میں ڈال لی۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کرلیں اور کہا: ”آج سے میں تمہیں پڑھاؤں گا اور اگر جماعت میں اول نہ لاسکا تو فرسٹ ڈویژن ضرور دلوا دوں گا۔ میرے ہر ارادے میں خدا وند تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور اس ہستی نے مجھے اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کیا….“
”مجھ سے پڑھائی نہ ہوگی۔“ میں نے گستاخی سے بات کاٹی۔
”تو او ر کیا ہوگا گولو؟“ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔
میں نے کہا: ”میں بزنس کروں گا، روپیہ کماؤں گا اور اپنی کار لے کر یہاں ضرور آؤں گا، پھر دیکھنا….“
اب کے داؤ جی نے میری بات کاٹی اور بڑی محبت سے کہا: ”خدا ایک چھوڑ تجھے دس کاریں دے لیکن ایک ان پڑھ کی کار میں نہ میں بیٹھوں گا، نہ ڈاکٹر صاحب۔“
میں نے جل کر کہا: ”مجھے کسی کی پروا نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر راضی، میں اپنے یہاں خوش۔“
انہوں نے حیران ہو کر پوچھا: ”میری بھی پرواہ نہیں؟“ میں کچھ کہنے ہی والاتھا کہ وہ دکھی سے ہوگئے اور بار بار پوچھنے لگے:
”میری بھی پرواہ نہیں؟“
”او گولو میری بھی پرواہ نہیں؟“
مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا: ”آپ کی تو ہے مگر….“ مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے اگر اپنے حضرت کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی؟ اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا…. تو …. تو….“
انہوں نے فورا پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہاتھ جوڑ کہنے لگے: ”میں حضور کے دربار کا ایک ادنیٰ کتا۔ میں حضرت مولانا کی خاک پا سے بد تر بندہ ہوکر آقا سے یہ کہتا۔ لعنت کا طوق نہ پہنتا؟ خاندانِ ابو جہل کا خانوادہ اور آقا کی ایک نظر کرم۔ حضرت کا ایک اشارہ۔ حضور نے چنتو کو منشی رام بنادیا۔ لوگ کہتے ہیں منشی جی، میں کہتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کا کفش بردار…. لوگ سمجھتے ہیں….“
داؤ جی کبھی ہاتھ جوڑتے، کبھی سر جھکاتے۔ کبھی انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے اشعار پڑھتے جاتے۔ میں کچھ پریشان سا پشیمان سا، ان کا زانو چھوکر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا: ”داؤ جی! داؤ جی“ اور داؤ جی ”میرے آقا، میرے مولانا، میرے مرشد“ کا وظیفہ کیے جاتے۔
جب جذب کا یہ عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھاکر بولے: ”کیا اچھا موسم ہے، دن بھر دھوپ پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے۔“ پھر وہ پل کی دیوار سے اٹھے اور بولے: ”چلو اب چلیں بازار سے تھوڑا سودا خریدنا ہے۔“
میں جیسا سرکش و بد مزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ منفعل اور خجل ان کے ساتھ لوٹا۔ گھمسے پنساری یعنی دیسو یب یب کے باپ کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضرورت کی چند چیزیں خریدیں اور لفافے گود میں اٹھا کر چل دئیے۔ میں بار بار ان سے لفافے لینے کی کوشش کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ ایک عجیب سی شرم ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانع تھی اوراسی تامل اور جھجک میں ڈوبتا ابھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا۔
وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کرو ں گا اور وہیں پڑھا کروں گا۔ کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی ہمارے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک برمی کین لالٹین بھی رکھی تھی۔
بزنس مین بننا اور پاں پاں کرتی پیکارڈ اُڑائے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انار کلی میں ہمارا دفتر، پتا نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہوچکا ہوتا۔
داؤ جی نے میری زندگی اجیرن کردی، مجھے تباہ کردیا، مجھ پر جینا حرام کردیا۔ سارا دن سکول کی بکواس میں گزرتا اور رات، گرمیوں کی مختصر رات، ان کے سوالات کا جواب دینے۔ کوٹھے پر ان کی کھاٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور وہ مونگ، رسول اور مرالہ کی نہروں کے بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بالکل ٹھیک بتادیا ہے۔ وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ میں نے پھر ٹھیک بتا دیا ہے اور انہوں نے پھر انہی نہروں کو آگے لاکھڑا کیا ہے۔میں جل جاتا اورجھڑک کر کہتا: ”مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتاتا“ تو وہ خاموش ہوجاتے اوردم سادھ لیتے، میں آنکھیں بند کرکے سونے کی کوشش کرتا تو وہ شرمندگی کنکر بن کر پتلیوں میں اتر جاتی۔
میں آہستہ سے کہتا: ”داؤ جی۔“
”ہوں۔“ ایک گھمبیر سی آواز آتی۔
’دداؤ جی کچھ اور پوچھو۔“
داؤ جی نے کہا: ”بہت بے آبرو ہوکر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس کی ترکیب نحوی کرو۔“
میں نے سعادت مندی کے ساتھ کہا: ”جی یہ تو بہت لمبا فقرہ ہے، صبح لکھ کر بتا دوں گا کوئی اور پوچھیے۔“
انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اُٹھائے کہا: ”میرا گولو بہت اچھا ہے۔“
میں نے ذر اسوچ کر کہنا شروع کیا بہت اچھا صفت ہے، حرف ربط مل کر بنا مسند….
اور داؤ جی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہاتھ اٹھاکر بولے: جانِ پدر، تجھے پہلے بھی کہا ہے مسند الیہ پہلے بنایا کر۔
میں نے ترکیبِ نحوی سے جان چھڑانے کے لیے پوچھا: ”آپ مجھے جانِ پدر کیوں کہتے ہیں، جانِ داؤ کیوں نہیں کہتے؟“
”شاباش“ وہ خوش ہوکرکہتے۔ ”ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشاکا۔ ان کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتی۔ جو لوگ دن بدن لکھتے یا بولتے ہیں، سخت غلطی کرتے ہیں، روز بروز کہو یا دن پر دن اسی طرح سے….“
اورجب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیبِ نحوی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں الجھ گیا ہوں تو جمائی لے کر پیار سے کہا ”داؤ جی اب تو نیند آرہی ہے!“
”اور وہ ترکیب نحوی؟“ وہ جھٹ سے پوچھتے۔۔۔
اس کے بعد چاہے میں لاکھ بہانے کرتا، ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا، مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے بیٹھے رہتے، بلکہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھاکر سر پر دھر لیتے۔ چنانچہ کچھ بھی ہوتا۔ ان کے ہر سوال کا خاطر خواہ جواب دینا پڑتا۔
امی چند کالج چلا گیا تو اس کی بیٹھک مجھے مل گئی اور داؤ جی کے دل میں اس کی محبت پر بھی میں نے قبضہ کرلیا۔ اب مجھے داؤ جی بہت اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ان کی باتیں جو اس وقت مجھے بری لگتی تھیں، وہ اب بھی بری لگتی ہیں بلکہ اب پہلے سے بھی کسی قدر زیادہ، شاید اس لیے کہ میں نفسیات کا ایک ہونہار طالب علم ہوں اور داؤ جی پرانے مُلّائی مکتب کے پروردہ تھے۔ سب سے بری عادت ان کی اٹھتے بیٹھتے سوال پوچھتے رہنے کی تھی اور دوسری کھیل کود سے منع کرنے کی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ آدمی پڑھتا رہے پڑھتارہے اور جب اس مدقوق کی موت کا دن قریب آئے تو کتابوں کے ڈھیر پر جان دے دے۔ صحتِ جسمانی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی نسخہ تھا، لمبی سیر اور وہ بھی صبح کی۔ تقریباً سورج نکلنے سے دو گھنٹے پیشتر وہ مجھے بیٹھک میں جگانے آتے اور کندھا ہلاکر کہتے: ”اٹھو گولو موٹا ہوگیا بیٹا۔“
دنیاجہاں کے والدین صبح جگانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا صبح ہوگئی یا سورج نکل آیا مگر وہ ”موٹا ہو گیا“ کہہ کر میری تذلیل کیا کرتے۔ میں منمناتا توچمکار کر کہتے: ”بھدا ہوجائے گا بیٹا تو، گھوڑے پر ضلع کا دورہ کیسا کرے گا!“ اور میں گرم گرم بستر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا: ” داؤ جی خدا کے لیے مجھے صبح نہ جگاؤ، چاہے مجھے قتل کردو، جان سے مار ڈالو۔“
یہ فقرہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ فوراً میرے سر پر لحاف ڈال دیتے اور باہر نکل جاتے۔
بے بے کو ان داؤ جی سے اللہ واسطے کا بیر تھا اور داؤ جی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ سارا دن محلے والیوں کے کپڑے سیا کرتیں اور داؤ جی کو کوسنے دئیے جاتیں۔ ان کی اس زبان درازی پرمجھے بڑا غصہ آتا تھا مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہ ہوسکتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ ناگفتنی گالیوں پر اتر آتیں تو داؤ جی میری بیٹھک میں آجاتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے: ”غیبت کرنا بڑا گناہ ہے لیکن میرا خدا مجھے معاف کرے تیری بے بے بھٹیارن ہے اور اس کی سرائے میں، میں، میری قرۃ العین اور تھوڑا تھوڑا، توبھی، ہم تینوں بڑے عاجز مسافر ہیں۔“
اور واقعی بے بے بھٹیارن سی تھی۔ ان کا رنگ سخت کالا تھا اور دانت بے حد سفید، ماتھا محراب دار اور آنکھیں چنیاں سی۔ چلتی تو ایسی گربہ پائی کے ساتھ جیسے (خدا مجھے معاف کرے) کٹنی کنسوئیاں لیتی پھرتی ہے۔ بچاری بی بی کو ایسی ایسی بری باتیں کہتی کہ وہ دو دو دن رو رو کر ہلکان ہوا کرتی۔ ایک امی چند کے ساتھ اس کی بنتی تھی۔ شاید اس وجہ سے کہ دونوں ہم شکل تھے یا شاید اس وجہ سے کہ اس کو بی بی کی طرح اپنے داؤ جی سے پیار نہ تھا۔
یوں تو بی بی بے چاری بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس سے میری بھی نہ بنتی۔ میں کوٹھے پر بیٹھا سوال نکال رہا ہوں، داؤ جی نیچے بیٹھے ہیں اور بی بی اوپر برساتی سے ایندھن لینے آئی تو ذرا رک کر مجھے دیکھا، پھر منڈیر سے جھانک کر بولی: ”داؤ جی! پڑھ تونہیں رہا، تنکوں کی طرح چارپائیاں بنارہا ہے۔“
میں غصیل بچے کی طرح منہ چڑا کر کہتا: ”تجھے کیا، نہیں پڑھتا، تو کیوں بڑ بڑ کرتی ہے…. آئی بڑی تھانیدارنی۔“
اور داؤ جی نیچے سے ہانک لگاکر کہتے: ”نہ گولو مولو، بہنوں سے جھگڑا نہیں کرتے۔“
اور میں زور سے چلاتا: ”پڑھ رہا ہوں جی، جھوٹ بولتی ہے۔“
داؤ جی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آجاتے اور کاپیوں کے نیچے نیم پوشیدہ چارپائیاں دیکھ کر کہتے: ”قرۃ بیٹا تو اس کو چڑایا نہ کر۔ یہ جن بڑی مشکل سے قابو کیاہے۔ اگر ایک بار بگڑ گیا تو مشکل سے سنبھلے گا۔“
بی بی کہتی: ”کاپی اٹھا کر دیکھ لو داؤ جی، اس کے نیچے ہے وہ چارپائی جس سے کھیل رہا تھا۔“
میں قہر آلود نگاہوں سے بی بی کو دیکھتا اور وہ لکڑیاں اٹھاکر نیچے اتر جاتی۔ پھر داؤ جی سمجھاتے کہ بی بی یہ کچھ تیرے فائدے کے لیے کہتی ہے ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ مجھے بتاتی پھرے۔ فیل ہویا پاس اس کی بلا سے! مگر وہ تیری بھلائی چاہتی ہے، تیری بہتری چاہتی ہے اور داؤ جی کی یہ بات ہر گز سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میری شکایتیں کرنے والی میری بھلائی کیونکر چاہ سکتی تھی!۔
ان دنوں معمول یہ تھا کہ صبح دس بجے سے پہلے داؤ جی کے ہاں سے چل دیتا۔ گھر جاکر ناشتہ کرتا اور پھر سکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا سکول بھیج دیا جاتا اور شام کو سکول بند ہونے پر گھر آکے لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے یہاں آجاتا۔ پھر رات کا کھانا بھی مجھے داؤ جی کے گھر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن ایام میں منصفی بند ہوتی، داؤ جی سکول کے گراؤنڈ میں آکر بیٹھ جاتے اور میرا انتظار کرنے لگتے۔ وہاں سے گھر تک سوالات کی بوچھاڑ رہتی۔ سکول میں جو کچھ پڑھایا گیا ہوتا اس کی تفصیل پوچھتے، پھر مجھے گھر تک چھوڑ کر خود سیر کو چلے جاتے۔
ہمارے قصبہ میں منصفی کا کام مہینے میں دس دن ہوتا تھا اور بیس دن منصف صاحب بہادر کی کچہری ضلع میں رہتی تھی۔ یہ دس دن داؤ جی باقاعدہ کچہری میں گزارتے تھے۔ ایک آدھ عرضی آجاتی تو دو چار روپے کمالیتے ورنہ فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالعہ کا سلسلہ جاری رکھتے۔ بے بے کا کام اچھا تھا۔ اس کی کتربیونت اور محلے والوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ پچھلے چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہوگئی تھی…. ایک دن خلاف معمول داؤ جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ اس وقت کچہری بند ہوگئی تھی اور داؤ جی نانبائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ہولے سے جاکر ان کا بستہ اٹھا لیا اور ان کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا: ”چلیے، آج میں آپ کو لینے آیا ہوں۔“ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنہ جیب سے نکال کر نانبائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دئیے۔
میں نے شرارت سے ناچ کر کہا: ”گھر چلیے، بے بے کو بتاؤں گا کہ آپ چوری چوری یہاں چائے پیتے ہیں۔“
داؤ جی جیسے شرمندگی ٹالنے کو مسکرائے اور بولے: ”اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور گڑ کی چائے سے تھکن بھی دور ہوجاتی ہے۔ پھر یہ ایک آنہ میں گلاس بھر کے دیتا ہے۔ تم اپنی بے بے سے نہ کہنا، خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کردے گی۔“
پھر انہوں نے خوفزدہ ہوکر کچھ مایوس ہوکر کہا: ”اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے“۔
اس دن مجھے داؤ جی پر رحم آیا۔ میرا جی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگا مگر اس میں میں نے بے بے سے نہ کہنے کا ہی وعدہ کرکے ان کے کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب اس واقعہ کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ بھی کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داؤ جی کے ہاں دودھ، پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگیں، مگر اس رسد سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ ہاں بے بے کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اور اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ شروع کردیا۔
مجھے یاد ہے، ایک صبح میں دودھ سے بھرا تاملوٹ ان کے یہاں لے کرآیا تھا اور بے بے گھر نہ تھی۔ وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ بابا ساون کے جوہڑ میں اشنان کرنے گئی تھی اور گھر میں صرف داؤ جی اور بی بی تھے۔ دودھ دیکھ کر داؤ جی نے کہا ”چلو آج تینو ں چائے پئیں گے۔ میں دکان سے گڑ لے کر آتاہوں، تم پانی چولہے پر رکھو۔“ بی بی نے جلدی سے چولہا سلگایا۔ میں پتیلی میں پانی ڈال کر لایا اور پھر ہم دونوں وہیں چوکے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ داؤ جی گڑ لے کر آگئے تو انہوں نے کہا: ”تم دونوں اپنے اپنے کام پر بیٹھو چائے میں بناتا ہوں۔“ چنانچہ بی بی مشین چلانے لگی اور میں ڈائریکٹ اِن ڈائریکٹ کی مشقیں لکھنے لگا۔ داؤ جی چولہا بھی جھونکتے جاتے تھے اور عادت کے مطابق مجھے بھی اونچے اونچے بتاتے جاتے تھے۔
گلیلیو نے کہا: ”زمین سورج کے گرد گھومتی ہے“۔ گلیلیو نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ نہ لکھ دینا کہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پانی ابل رہا تھا داؤ جی خوش ہورہے تھے۔ اسی خوشی میں جھوم جھوم کر وہ اپنا تازہ بنایا ہوا گیت گا رہے تھے۔ ”او گولو! او گولو! گلیلیو کی بات مت بھولنا، گلیلیو کی بات مت بھولنا۔“ انہوں نے چائے کی پتی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ برتن ابھی تک چولہے پر ہی تھا اورداؤ جی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پانی کی گل بل گل بل کے ساتھ گولو گلیلیو! گولو گلیلیو کیے جارہے تھے۔ میں ہنس رہا تھا اور اپنا کام کیے جارہا تھا۔ بی بی مسکرارہی تھی اورمشین چلائی جاتی تھی اور ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھرمیں بڑے ہی خوش تھے۔ گویا سارے محلے بلکہ سارے قصبہ کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھرمیں اتر آئی ہوں۔۔۔
اتنے میں دروازہ کھلا اور بے بے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا رنگ فق ہوگیا۔ چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے اندر چائے کے چھوٹے چھوٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے پھرتے تھے اور ممنوع کھیل رچانے والا بڈھا موقع پر پگڑا گیا۔ بے بے نے آگے بڑھ کر چولہے کی طرف دیکھا اور داؤجی نے چوکے سے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا: ”چائے ہے!“
بے بے نے ایک دو ہتڑ داؤ جی کی کمر پر مارا اور کہا: ”بڈھے بروہا تجھے لاج نہیں آتی۔ تجھ پر بہار پھرے، تجھے یم سمیٹے، یہ تیرے چائے پینے کے دن ہیں۔ میں بیوہ گھر میں نہ تھی تو تجھے کسی کا ڈر نہ رہا۔ تیرے بھانویں میں کل کی مرتی آج مروں تیرا من راضی ہو۔ تیری آسیں پوری ہوں۔ کس مرن جوگی نے جنا اور کس لیکھ کی ریکھا نے میرے پلے باندھ دیا…. تجھے موت نہیں آتی…. اوں ہوں تجھے کیوں آئے گی۔“
اس فقرے کی گردان کرتے ہوئے بے بے بھیڑنی کی طرح چوکے پر چڑھی، کپڑے سے پتیلی پکڑ کر چولہے سے اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ گرم گرم چائے کے چھپاکے داؤ جی کی پنڈلیوں اور پاؤں پر گرے اور وہ ”اوہ تیرا بھلا ہو جائے۔ او تیرا بھلا ہوجائے۔“ کہتے وہاں سے ایک بچے کی طرح بھاگے اور بیٹھک میں گھس گئے۔ ان کے اس فرار بلکہ اندازِ فرار کو دیکھ کر میں اور بی بی ہنسے بنا نہ رہ سکے اور ہماری ہنسی کی آواز ایک ثانیہ کے لیے چاروں دیواروں سے ٹکرائی۔
میں تو خیر بچ گیا لیکن بے بے نے سیدھے جاکر بی بی کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیخ کر بولی: ”میری سوت بڈھے سے تیرا کیا ناطہ ہے۔ بتا نہیں تو اپنی پران لیتی ہوں۔ تو نے اس کو چائے کی کنجی کیوں دی؟“
بی بی بیچاری پھس پھس رونے لگی تو میں بھی اندر بیٹھک میں کھسک آیا۔ داؤ جی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور اپنے پاؤں سہلارہے تھے۔ پتا نہیں انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے پھرکیوں گدگدی ہوئی کہ میں الماری کے اندر منہ کرکے ہنسنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور بولے: ”شکرِ کردگار کنم کہ گرفتارم بہ مصیبتے نہ کہ معصیتے۔“
تھوڑی دیر رک کر پھر کہا: ”میں اس کے کتوں کا بھی کتا ہوں جس کے سرِ مُطہّر پر مکے کی ایک کم نصیب بڑھیا غلاظت پھینکا کرتی تھی۔“
میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے: ”آقائے نامدار کا ایک ادنیٰ حلقہ بگوش، گرم پانی کے چند چھینٹے پڑنے پر نالہ شیون کرے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ وہ اپنے محبوبﷺ کے طفیل نارِ جہنم سے بچائے۔ خدائے ابراہیمؑ مجھے جرأت عطا کرے، مولائے ایوبؑ مجھے صبر کی نعمت دے۔“
میں نے کہا: ”داؤ جی آقائے نامدار کون؟“
تو داؤ جی کو یہ سن کر ذرا تکلیف ہوئی۔ انہوں نے شفقت سے کہا: ”جان پدر! یوں نہ پوچھا کر۔ میرے استاد، میرے حضرت کی روح کو مجھ سے بیزار نہ کر، وہ میرے آقا بھی تھے، میرے باپ بھی اور میرے استاد بھی، وہ تیرے دادا استاد ہیں…. دادا استاد…“ اور انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آقائے نامدار کا لفظ اور کوتاہ قسمت مجوزہ کی ترکیب میں نے پہلی بار داؤ جی سے سنی۔ یہ واقعہ سنانے میں انہوں نے کنتی ہی دیر لگادی کیونکہ ایک ایک فقرے کے بعد فارسی کے بیشمار نعتیہ اشعار پڑھتے تھے اور بار بار اپنے استاد کی روح کو ثواب پہنچاتے تھے۔“
جب وہ یہ واقعہ بیان کرچکے تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا: ”داؤ جی آپ کو اپنے استاد صاحب اس قدر اچھے کیوں لگتےتھے اور آپ ان کا نام لے کر ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا نوکر کیوں کہتے ہیں؟“
داؤ جی نے مسکرا کر کہا: ”جو طویلے کے ایک خر کو ایسا بنادے کہ لوگ کہیں یہ منشی چنت رام جی ہیں۔ وہ مسیحا نہ ہو، آقا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟“
میں چارپائی کے کونے سے آہستہ آہستہ پھسل کر بسترمیں پہنچ گیا اور چاروں طرف رضائی لپیٹ کر داؤ جی کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکاکر کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی پنڈلیاں سہلاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد ذرا سا ہنستے اور پھر خاموش ہوجاتے….۔
کہنے لگے: ”میں تمہارا کیا تھا اور کیا ہوگیا…. حضرت مولانا کی پہلی آواز کیا تھی! میری طرف سر مبارک اٹھاکر فرمایا، چوپال زادے ہمارے پاس آؤ۔ میں لاٹھی ٹیکتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چھتہ پٹھار اور دیگر دیہات کے لڑکے نیم دائرہ بنائے ان کے سامنے بیٹھے سبق یاد کررہے تھے۔ ایک دربار لگا تھا اور کسی کو آنکھ اوپر اٹھانے کی ہمت نہ تھی…. میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا: بھئی ہم تم کو روز یہاں بکریاں چراتے دیکھتے ہیں۔ انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ کر ہمارے پاس آجایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو…. پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے گنواروں کی طرح کہا چنتو…. مسکرائے…. تھوڑا سا ہنسے بھی…. فرمانے لگے پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے چنتو رام ہوگا…. میں نے سر ہلا دیا…. حضور کے شاگرد کتاب سے نظریں چراکر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا سا کرتہ تھا۔ پائجامہ کی بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا۔ پاؤں میں ادھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگیہ لپیٹا ہوا تھا۔ ”بکریاں میری….“
میں نے بات کاٹ کرپوچھا: ”آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟“
”ہاں ہاں!“ وہ فخر سے بولے۔ ”میں گڈریا تھا اور میرے باپ کی بارہ بکریاں تھیں۔“
حیرانی سے میرا منہ کھلا رہ گیا اور میں نے معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھا: ”اور آپ سکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے؟“ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے: ”جان پدر اس زمانے میں تو شہروں میں بھی سکول نہیں ہوتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے چوہتر برس پہلے کوئی تمہارے ایم بی ہائی سکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا۔ ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے چار حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیج دیتے…. ان کا سارا خاندان زیورِ تعلیم سے آراستہ اور دینی اور دنیوی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے۔ جدِ امجد مہاراجہ کشمیر کے میر منشی۔ گھرمیں علم کے دریا بہتے تھے۔ فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، اقلیدس، حکمت اور علم ہیئت ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کے تبحرِ علمی کی سب داستانیں سنیں۔ شیفتہ اور حکیم مومن خاں مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے اورخود مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی آزردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی….“
مجھے داؤجی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا: ”پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کردیا؟“ ”ہاں“ داؤ جی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ”ان کی باتیں ہی ایسی تھیں۔ ان کی نگاہیں ہی ایسی تھیں جس کی طرف توجہ فرماتے تھے، بندے سے مولاکردیتے تھے۔ مٹی کے ذرے کو اکسیر کی خاصیت دے دیتے تھے…. میں تو ا پنی لاٹھی زمین پر ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے بوریے پر بیٹھو۔ میں نے کہا: جی اٹھارہ برس دھرتی پر بیٹھے گزر گئے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر مسکرا دئیے، اپنے چوبی صندوقچے سے حروف ابجد کا ایک مقوا نکالا اور بولے الف۔ بے۔ بے۔ تے….“ سبحان اللہ کیا آواز تھی۔ کس شفقت سے بو لے تھے۔ کس لہجہ میں فرما رہے تھے الف، بے، پے، ت “
اور داؤ جی ان حرفوں کا ورد کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھوگئے۔
تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا: ”ادھر رہٹ تھا اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا حوض۔“ پھر انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا: ”اور اس طرف مزارعین کے کوٹھے۔ دونوں کے درمیان حضور کا باغیچہ تھا اور سامنے ان کی عظیم الشان حویلی۔ اسی باغیچے میں ان کا مکتب تھا۔ درِ فیض کھلا تھا جس کا جی چاہے آئے، نہ مذہب کی قید نہ ملک کی پابندی….“
میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد با ادب با ملاحظہ قسم کا فقرہ تیار کرکے پوچھا: ”حضرت مولانا کا اسم گرامی شریف کیا تھا؟“ تو پہلے انہوں نے میرا فقرہ ٹھیک کیا اور پھر بولے۔ ”حضرت اسماعیل چشتی فرماتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہیں جانِ جاناں کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی جانِ جاناں کی رعایت سے مظہر جانِ جاناں بھی کہہ دیتے تھے۔“
میں ایسی دلچسپ کہانی سننے کا ابھی اور خواہش مند تھا کہ داؤ جی اچانک رک گئے اور بولے: ”سب سڈی ایری سسٹم کیا تھا؟ ان انگریزوں کا برا ہو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے یا ملکہ وکٹوریہ کا فرمان لے کر، سارے معاملے میں کھنڈت ڈال دیتے ہیں۔“ سوا کے پہاڑے کی طرح میں نے سب سڈی ایری سسٹم کا ڈھانچہ ان کی خدمت میں پیش کردیا۔ پھر انہوں نے میز سے گرائمر کی کتاب اٹھائی اور بولے: ”باہر جاکر دیکھ کے آ کہ تیری بے بے کا غصہ کم ہوا یا نہیں؟“
میں دوات میں پانی ڈالنے کے بہانے باہر گیا تو بے بے کو مشین چلاتے اور بی بی کو چکوا صاف کرتے پایا۔“
داؤ جی کی زندگی میں بے بے والا پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ گھر میں مطلع صاف ہے اور بے بے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے، تو وہ پکار کر کہتے: ”سب ایک ایک شعر سناؤ“ پہلے مجھی سے تقاضا ہوتا اور میں چھوٹتے ہی کہتا:
لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور
تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور
اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے: ”اولین شعر نہ سنوں گا، اردو کا کم سنوں گا اور مسلسل نظم کا ہر گز نہ سنوں گا۔“
بی بی بھی میر ی طرح اکثر اس شعر سے شروع کرتی۔
شنیدم کہ شاپور دم در کشید
چو خسرو بر آتش قلم در کشید
اس پر داؤ جی ایک مرتبہ پھر آرڈر آرڈر پکارتے۔
بی بی قینچی رکھ کر کہتی:
شورے شد و از خوابِ عدم چشم کشوریم
دیدیم کہ باقی ست شبِ فتنہ غنودیم
داؤ جی شاباش تو ضرور کہہ دیتے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے: ”بیٹا یہ شعر تُو کئی مرتبہ سناچکی ہے۔“
پھر وہ بے بے کی طرف دیکھ کر کہتے: ”بھئی آج تمہاری بے بے بھی ایک سنائے گی۔“ مگر بے بے روکھا سا جواب دیتی: ”مجھے نہیں آتے شیر، کبت“۔
اس پر داؤ جی کہتے: ”گھوڑیاں ہی سنادے۔ اپنے بیٹوں کے بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔“
اس پر بے بے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے لیکن وہ مسکرا نہ سکتی اور داؤ جی عین عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔ ان کے درمیان کبھی امی چند اور کبھی میرا نام ٹانک دیتے۔ پھر کہتے: ”میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا۔ برات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور نکاح نامے میں شہادت کے دستخط کروں گا۔
میں دستور کے مطابق شرماکر نگاہیں نیچی کرلیتا تو وہ کہتے: ”پتا نہیں اس ملک کے کسی شہر میں میری چھوٹی بہو پانچویں یا چھٹی جماعت میں پڑھ رہی ہوگی۔ ہفتہ میں ایک دن لڑکیوں کی خانہ داری ہوتی ہے۔ اس نے تو بہت سی چیزیں پکانی سیکھ لی ہو گی۔ پڑھنے میں بھی ہوشیار ہوگی۔ اس بدھو کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مادیاں گھوڑیاں ہوتی ہے یا مرغی۔ وہ تو فر فر سب کچھ سناتی ہوگی۔ میں تو اس کو فارسی پڑھاؤں گا۔ پہلے اس کو خطاطی کی تعلیم دوں گا پھر خطِ شکستہ سکھاؤں گا۔ مستورات کو خطِ شکستہ نہیں آتا۔ میں اپنی بہو کو سکھا دوں گا…. سن گولو! پھر میں تیرے پاس ہی رہوںگا۔ میں اور میری بہو فارسی میں باتیں کریں گے۔ وہ بات بات پر بفرمائید بفرمائید کہے گی اور تو احمقوں کی طرح منہ دیکھا کرے گا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ”خیلے خوب خیلے خوب“ کہتے۔ جانِ پدر چرا ایں قدر زحمت می کشی…. خوب…. یاد دارم…. اور پتا نہیں کیا کیا کچھ کہتے۔ بچارے داؤ جی! چٹائی پر اپنی چھوٹی سی دنیا بساکر اس میں فارسی کے فرمان جاری کیے جاتے….
ایک دن جب چھت پر دھوپ پر بیٹھے ہوئے وہ ایسی ہی دنیا بساچکے تھے تو ہولے سے مجھے کہنے لگے: ”جس طرح خدا نے تجھے ایک نیک سیرت بیوی اور مجھے سعادت مند بہو عطاکی ہے ویسے ہی وہ اپنے فضل سے میرے امی چند کو بھی دے۔“
اس کے خیالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے، یہ سوانگ، یہ مسلم لیگ یہ بیلچہ پارٹیاں مجھے پسند نہیں اور امی چند لاٹھی چلانا گٹکا کھیلنا سیکھ رہا ہے۔ میری تو وہ کب مانے گا۔ ہاں خدائے بزرگ و برتر اس کو ایک نیک مومن سی بیوی دلا دے تو وہ اسے راہِ راست پر لے آئے گی۔“
اس مومن کے لفظ پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اورمیں چپ سا ہوگیا۔ چپ محض اس لیے ہوا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یقیناً ایسی بات نکلے گی جس سے داؤ جی کو بڑا دکھ ہوگا…. میری اور امی چند کی تو خیر باتیں ہی تھیں، لیکن بارہ جنوری کو بی بی کی برات سچ مچ آگئی۔ جیجا جی رام پرتاب کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتاچکے تھے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بارہ تاریخ کی شام کو بی بی وداع ہونے لگی تو گھر بھرمیں کہرام مچ گیا۔ بے بے زار و قطار رو رہی ہے۔ امی چند آنسو بہا رہا ہے اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور باربار کہہ رہے ہیں آج زمین کچھ میرے پاؤ ں نہیں پکڑتی۔ میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے: ”منشی جی اب ہمیں اجازت دیجیے“ تو بی بی پچھاڑ کر گر پڑی۔ اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا: ”یہ کیا ہوا بیٹا۔ اٹھو! یہ تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے۔ اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔“ بی بی اس طرح دھاڑیں مارتے ہوئے داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: ”قرۃ العین میں تیرا گنہگار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا۔ تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کردے گی اور شاید برخوردار رام پرتاب بھی لیکن میں اپنے کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا خجل سر تیرے سامنے خم ہے۔“
یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے کتنے سارے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا: ”منشی جی آپ فکر نہ کریں میں بیٹی کو کریما پڑھا دوں گا۔“ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑکر کہا: ”کریما تو یہ پڑھ چکی ہے، گلستان بوستان بھی ختم کر چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔“ اس پر وہ ہنس کر بولے: ”ساری گلستان تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی، آگے گزر جاتا تھا….“ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے، بی بی نے گوٹہ لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سکھیوں کے بازوؤں میں ڈیوڑھی کی طرف چل دی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر کہا: ”یہ لو یہ بھی رو رہا ہے۔ دیکھو ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ اوگولو…. او مردم دیدہ…. تجھے کیا ہو گیا…. جانِ پدر تو کیوں….“
اس پر ان کا گلا رندھ گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہوگئے۔ برات والے تانگوں اور اِکوں پر سوار تھے۔ بی بی رتھ میں جارہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں اور ہمارے درمیان میں داؤجی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھا تے او ر کہتے: ”لا حول پڑھو بیٹا، لاحول پڑھو۔“ اور خود آنکھوں پر رکھے رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔
رانو ہمارے محلے کا کثیف سا انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھر ی تھی۔ وہ باڑہ جس کا میں نے ذکر کیاہے، اسی کا تھا۔ اس میں بیس تیس بکریاں اور گائیں تھیں جن کا دودھ صبح و شام رانو گلی کے بغلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یونہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو ”پنڈتا جے رام جی کی“ کہہ کر سلام کیا کرتا۔
داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا بھی کہ وہ پنڈت نہیں ہیں معمولی آدمی ہیں کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک بڑے پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ کو چباکر کہتا: ”ارے بھئی جس کے سر پر بودی (چٹیا) ہو وہی پنڈت ہوتا ہے….“
چوروں یاروں سے اس کی آشنائی تھی شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا اور گندی اور فحش بولیوں کا مشاعرہ۔ بی بی کے جانے کے ایک دن بعد جب میں اس سے سے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے آنکھ میچ کر کہا: ”مورنی تو چلی گئی بابو اب تو اس گھر میں رہ کر کیا لے گا؟“ میں چپ رہا تو اس نے جھاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا: ”گھر میں گنگا بہتی تھی سچ بتا کہ غوطہ لگایا کہ نہیں؟“
مجھے اس بات پر غصہ آگیا اور میں نے تاملوٹ گھماکر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضربِ شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہ ہوا لیکن وہ چکراکر تخت پر گرپڑا اور میں بھاگ گیا۔ داؤ جی کو سارا واقعہ سناکر میں دوڑا دوڑا اپنے گھرگیا اور ابا جی سے ساری حکایت بیان کی۔ ان کی بدولت رانو کی تھانہ میں طلبی ہوئی اور حوالدار صاحب نے ہلکی سی گو شمالی کے بعد اسے سخت تنبیہ کرکے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد رانو دا ؤجی پر آتے جاتے طرح طرح کے فقرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا تھا اور واقعی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا اچھی نہ لگتی تھی۔ مگر وہ کہتے تھے: ”یہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز ہے۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کر اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگاکر چمکاتی تھی۔ گو میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے اور جب میں دیال سنگھ میموریل ہائی سکول سے ایک سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا: ”شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟“ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے اور ہم ساخوش قسمت استاد بھی خال خال ہوگا جسے تم ایسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کر فرمانے لگے چنت رام ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے لمس کا کیافائدہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ میں نے کہا اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں۔ میں اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نذر کردوں لیکن میرا بس نہیں چلتا…. خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی سہی۔ تم سلامت رہو کہ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی دس سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا ہے….“ داؤ جی گزرے ایام کی تہہ میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے۔
”میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڑھی میں جا کر آواز دیتا ”خادم آگیا“ مستورات ایک طرف ہو جاتیں تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی طرف بڑھتا۔ پاؤں چھوتا اور پھر حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت فرماتے اور پھر کہتے: ”لو بھئی چنت رام ان گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھالو۔“ میں سبدِ گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آجاتا۔ کبھی فرماتے، ہمیں باغ کا چکر دو کبھی حکم ہوتا سیدھے رہٹ کے پاس لے چلو اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے چنت رام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے، یہی فرماتے رہے کہ کبھی جی چاہتا ہے تو تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میں وضو کرنے والے چبوترے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے دیکھا تھا اس کے بعد جرأت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن میں منہ چھپا لیتا اور پھر اسی وقت سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبے کی لمبی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا۔ تو فرماتے ہم جانتے ہیں چنت رام تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبہ کی سیر کراتے ہو لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا لدا پھرتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہما ہے دوسرے تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں۔ اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطۂ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔
اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی ایک ہماہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کردیا ہے…. جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا، اس قدر خوش ہوئے گویا ہفت اقلیم کی بادشاہی نصیب ہو گئی۔ دین و دنیا کی ہر دعا سے مجھے مالا مال کیا۔ دستِ شفقت میرے سر پر پھیرا اور جیب سے ایک روپیہ نکال کر انعام دیا۔ میں نے اسے حجرِ اسود جان کر بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاکر دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے جو کام ہم سے نہ ہوسکا، وہ تو نے کردکھایا۔ تو نیک ہے خدا نے تجھے یہ سعادت نصیب کی۔ چنت رام تیرا مویشی چرانا پیشہ ہے تُو شاہ بطحا کا پیرو ہے، اس لیے خدائے عز و جل تجھے برکت دیتا ہے وہ تجھے اور بھی برکت دے گا۔ تجھے اور کشائش میسر آئے گی….“
داؤ جی یہ باتیں کرتے کرتے گھٹنوں پر سر رکھ کر خاموش ہوگئے۔
میرا امتحان قریب آرہا تھا اور داؤ جی سخت ہوتے جارہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر فارغ وقت پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا۔ ایک مضمون سے عہدہ برا ہوتا تو دوسرے کی کتابیں نکال کر سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ پانی پینے اٹھتا تو سایہ کی طرح ساتھ ساتھ چلے آتے اور نہیں تو تاریخ کے سن ہی پوچھتے جاتے۔ شام کے وقت سکول پہنچنے کا انہوں نے وطیرہ بنالیا تھا۔ ایک دن میں سکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کی بجائے بورڈنگ کی راہ پر کھسک لیا تو انہوں نے جماعت کے کمرے کے سامنے آکر بیٹھنا شروع کردیا۔ میں چڑچڑا اور ضدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہوگیا تھا۔ ”داؤ جی“ کے بچے، گویا میرا تکیہ کلام بن گیا تھا اور کبھی کبھی جب ان کی یا ان کے سوالات کی سختی بڑھ جاتی تو میں انہیں کتے کہنے سے بھی نہ چوکتا۔ ناراض ہو جاتے تو بس اس قدر کہتے: ”دیکھ لے ڈومنی تو کیسی باتیں کررہاہے۔ تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہی بتاؤں گا کہ جانِ پدر یہ تیرے باپ کو کتا کہتا تھا۔“
میری گالیوں کے بدلے وہ مجھے ڈومنی کہا کرتے تھے۔ اگر انہیں زیادہ دکھ ہوتا تو منہ چڑی ڈومنی کہتے۔ اس سے زیادہ نہ انہیں غصہ آتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا۔ میرے اصلی نام سے انہوں نے کبھی نہیں پکارا۔ میرے بڑے بھائی کا ذکر آتا تو بیٹا آفتاب، برخوردار آفتاب کہہ کر انہیں یاد کرتے تھے لیکن میرے ہر روز نئے نئے نام رکھتے تھے۔ جن میں گولو انہیں بہت مرغوب تھا۔ طنبورا دوسرے درجہ پر، مسٹرہونق اور اخفش اسکوائر ان سب کے بعد آتے تھے اور ڈومنی صرف غصہ کی حالت میں۔ کبھی کبھی میں ان کو بہت دق کرتا۔ وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہان کی ابجد کو ضرب دے دے کر تنگ آچکا ہوں تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے لگتا:
تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نیو دسنا
دا ؤ جی حیرانی سے میری طرف دیکھتے تو میں تالیاں بجانے لگتا اور قوالی شروع کردیتا۔ نیوں نیوں نیوں دسنا۔ تے دکھ تینوں نیوں دسنا…. دسنا دسنا دسنا…. تینوں تینوں تینوں۔ سارے گاما رونا رونا سارے گاما رونا رونا…. تے دیکھ تینوں نیوں دسنا۔ وہ عینک کے اوپر سے مسکراتے۔ میرے پاس آکر کاپی اٹھاتے، صفحہ نکالتے اور تالیوں کے درمیان اپنا بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیتے۔
”سن بیٹا“ وہ بڑی محبت سے کہتے۔ ” یہ کوئی مشکل سوال ہے!“ جونہی وہ سوال سمجھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے میں پھر تالیاں بجانے لگتا۔ ”دیکھ پھر، میں تیرا داؤ نہیں ہو؟“ وہ بڑے مان سے پوچھتے۔
”نہیں“ میں منہ پھاڑ کر کہتا۔
” تو اور کون ہے ؟“ وہ مایوس سے ہو جاتے۔
”وہ سچی سرکار“ میں انگلی آسمان کی طرف کر کے شرارت سے کہتا۔ وہ سچی سرکار، وہ سب کا پالنے والا…. بول بکرے سب کا والی کون؟“
وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے تو میں ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا ”داؤ جی خفا ہوگئے کیا؟“
وہ مسکرانے لگتے۔ ”چھوڑ طنبورے! چھوڑ بیٹا! میں تو پانی پینے جارہا تھا…. مجھے پانی تو پی آنے دے۔
میں جھوٹ موٹ برامان کر کہتا: ”لوجی جب مجھے سوال سمجھنا ہوا داؤ جی کو پانی یاد آگیا۔“
وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور کاپی کھول کر کہتے: ”اخفش اسکوائر جب تجھے چار ایکس کا مربع نظر آرہا تھا تو تو نے تیسرا فارمولا کیوں نہ لگایا اور اگر ایسا نہ بھی کرتا تو….“اور اس کے بعد پتا نہیں داؤ جی کتنے دن پانی نہ پیتے۔
فروری کے دوسرے ہفتہ کی بات ہے۔ امتحان میں کل ڈیڑھ مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کردی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا کُل باون پراپوزیشنیں ہیں زبانی یاد کرلے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں انہیں رٹنے میں مصروف ہوگیا، لیکن جو پراپوزیشن رات کو یاد کرتا، صبح کو بھول جاتا۔
میں دل برداشتہ ہوکر ہمت چھوڑ سی بیٹھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنواکر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہوگئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کرکے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر پھر بیٹھ گیا اور رات کے ڈیڑھ بجے تک لکھ لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگتا تو چند فقروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کرکے اور اپنی حالت کا اندازہ کرکے رونا آگیا اور میں باہر صحن میں آکر سیڑھیوں پر بیٹھ کے سچ مچ رونے لگا۔ گھٹنوں پر سر رکھے رورہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوڑھی کا دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ جب یہ فیصلہ کرچکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑھے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو سسکیوں کا لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔
داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا: ”لے بھئی طنبورے میں تو یوں نہ سمجھتا تھا تو تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔“
پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے آئے۔ بستر میں بٹھاکر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں اوپر کرکے کرسی پر بیٹھ گئے۔
انہوں نے کہا: ”اقلیدس چیز ہی ایسی ہے۔ تو اس کے ہاتھوں یوں نالاں ہے۔ میں اس سے اور طرح تنگ ہوا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر و مقابلہ اور اقلیدس کی جس قدر کتابیں تھیں، انہیں میں اچھی طرح پڑھ کر اپنی کاپیوں پر اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہوگیا ہوں لیکن ایک رات میں اپنی کھاٹ پر پڑا متساوی الساقلین کے ایک مسئلہ پر غور کررہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلاکر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کی رو سے اس کاجواب ٹھیک آتا تھا لیکن علمِ ہندسہ سے پایۂ ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا لیکن تیری طرح سے رویا نہیں۔
علی الصبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دستِ مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی طبعِ رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے: ”چنت رام اب ہم تم کو نہیں پڑھاسکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہوجائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔“
میں نے جرأت کرکے کہہ دیا کہ حضور اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکمِ ربانی سے کم نہیں۔ اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقائے غزنوی کے سامنے ایاز کی مجال! لیکن حضور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ فرمانے لگے: ”تم بے حد جذباتی آدمی ہو۔ بات تو سن لی ہوتی۔“ میں نے سر جھکاکر کہا ارشاد! فرمایا: ”دلی میں حکیم ناصر علی سیستانی علمِ ہندسہ کے بڑے ماہر ہیں۔ اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتسابِ علم کرو۔ ہم ان کے نام رقعہ لکھ دیں گے۔“ میں نے رضا مندی ظاہر کی تو فرمایا اپنی والدہ سے پوچھ لینا اگر وہ رضامند ہوں تو ہمارے پاس آنا…. والدہ مرحومہ سے پوچھا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی۔ چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔
حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ ”گھر کی لپائی تپائی کررہا ہوں۔ جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔“
چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس شکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لا ینحل مسئلہ سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا لیکن حضور سے اجازت مل سکتی تھی نہ رقعہ، وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے اور والدہ اس بڑھاپا میں کیسے آمادہ ہوسکتی تھیں….
ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اورمیں تیری طرح پریشان تھا تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی دو روپے چرائے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے! واقعی میں نے بڑا گناہ کیا اور ابد تک میرا سر ان دونوں کرمفرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا…. گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کی مسند کے پاس پہنچا جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہوکرمیں نے زمین کو بوسہ دیا اور دل میں کہا: ”بدقسمت ہوں، بے اجازت جارہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آکے قدموں میں جان دے دوں گا۔“
اتنا کہہ کر اٹھا اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر میں وہاں سے چل دیا…. ”سن رہا ہے؟“ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔
رضائی کے بیچ خارپشت بنے، میں نے آنکھیں جھپکائیں اور ہولے سے کہا: ”جی!“
داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا: ”قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسہ حصار والی پٹڑی بن رہی تھی۔ یہی راستہ سیدھا دلی کو جاتا تھا اور یہیں مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرتا اور ایک دن چلتا، اس طرح تائیدِ غیبی کے سہارے سولہ دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آگئی تھی لیکن گوہرِ مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حکیم ناصر علی سیستانی کا دولت خانہ کہاں ہے، نفی میں جواب ملتا۔ دو دن ان کی تلاش جاری رہی لیکن پتا نہ پاسکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی۔ انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھیں۔ وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہوکر حکیم صاحب کا پتا معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پھینک کر گہری نیند سوجاتا۔ مثل مشہور ہے جویندہ یابندہ! آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہوگئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلہ کی ایک تیرہ و تاریک گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں فروکش تھے اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہورہی تھی۔ میں جوتے اتارکر دہلیز کے اندر کھڑا ہوگیا۔ ایک صاحب نے پوچھا: ”کون ہے؟“ میں نے سلام کرکے کہا۔ ”حکیم صاحب سے ملنا ہے۔“
حکیم صاحب دوستوں کے حلقہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بولے: ”اسم گرامی؟“ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ”پنجاب سے آیا ہوں اور….“ میں بات پوری بھی نہ کرپایا تھا کہ زور سے بولے: ”اوہو! چنت رام ہو؟“ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے: ”مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنت رام تمہارے پاس آئے۔ ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہوگیا ہے، اس کی مدد کرنا۔“
میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹ دار آواز میں بولے: ”میاں! اندر آجاؤ، کیا چپ کا روزہ رکھا ہے؟“
میں ذرا آگے بڑھا تو بھی میری طرف نہ دیکھا اور ویسے ہی عروسِ نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے تحکمانہ انداز میں کہا: ”برخوردار بیٹھ جاؤ۔“
میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا: ”بھئی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے دو دو ہاتھ کرلینے دو۔“ پھر حکم ہوا ”بتاؤ ہندسہ کا کونسا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟“
میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ آہستہ کُرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہوگئی۔ پھر فرمایا: ”بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر ایک متساوی الساقین۔“
مجھ پر سکتہ کا عالم طاری تھا۔ نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحہ کے بعد بولے: ”میاں جلدی کرو۔ نابینا ہوں۔ کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔“ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر ہانپتی ہوئی انگلیوں سے متساوی الساقین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مرئی شکل بن چکی تو بولے اب اس نقطہ ”س“ سے خط ”ب ج“پر عمود گراؤ۔“
ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا دوسرے وہاں کچھ نہ آتا تھا۔ یونہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے ”ہے ہے کیا کرتے ہو یہ نقطہ ہے کیا؟“
پھر خود ہی بولے ”آہستہ آہستہ عادی ہوجاؤ گے۔“ وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیر متساوی الساقین بن کر ان کی کمر پر ابھر آئیں گی۔
پھر داؤ جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے بے چین ہوکر پوچھا: ”پھر کیا ہوا داؤ جی؟“ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا: ”رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا پھر بتاؤں گا۔“
میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑگیا تو انہوں نے کہا: ”پہلے وعدہ کر کہ آیندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پراپوزیشنوں کو پتاشے سمجھے گا۔“
میں نے جواب دیا: ”حلوہ سمجھوں گا آپ فکر نہ کریں۔“
انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا: ”بس مختصر یہ کہ میں ایک سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحرِعلم سے چند قطرے حاصل کرکے اپنی کور آنکھوں کو دھویا۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فرمانے لگے: چنت رام اگر ہم میں قوت ہو تو ان پاؤں کوکھینچ لیں۔ اس پر میں رو دیا تو دستِ مبارک محبت سے میرے سر پر پھیرکر کہنے لگے: ”ہم تم سے ناراض نہیں ہیں لیکن ایک سال کی فرقت بہت طویل ہے۔ آیندہ کہیں جانا ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔“ یہ کہتے ہوئے داؤ جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ مجھے اسی طرح گم سم چھوڑ کر بیٹھک میں چلے گئے۔“
امتحان کی قربت سے میرا خون خشک ہورہا تھا، لیکن جسم پھول رہا تھا۔ داؤ جی کو میرے موٹاپے کی فکر رہنے لگی۔ اکثر میرے تھن متھنے ہاتھ پکڑ کر کہتے: ”اسپِ تازی بن طویلہ خر نہ بن۔“ مجھے ان کا یہ فقرہ بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجاً ان سے کلام بند کردیتا۔ میرے مسلسل مرن برت نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا اور ان کی فکر، اندیشہ کی حد تک بڑھ گئی۔ ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے آجگایا اور میری منتوں، خوشامدوں، گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کوٹ پہناکر کھڑا کردیا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گویاگھسیٹتے ہوئے باہر گئے۔ سردیوں کی صبح کوئی چار بجے کا عمل۔ گلی میں آدم نہ آدم زاد، تاریکی سے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور داؤ جی مجھے اسی طرح سیر کو لے جارہے تھے۔ میں کچھ بک رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ابھی گراں خوابی دور نہیں ہوئی ابھی طنبورا بڑبڑا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد کہتے کوئی سر نکال طنبورے کی آہنگ پر بجا یہ کیا کر رہا ہے!
جب ہم بستی سے دور نکل گئے اور صبح کی یخ ہوا نے میری آنکھوں کو زبردستی کھول دیا تو داؤ جی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ سرداروں کا رہٹ آیا اور نکل گیا۔ ندی آئی اور پیچھے رہ گئی۔ قبرستان گزر گیا مگر داؤ جی تھے کہ کچھ آیتیں ہی پڑھتے چلے جارہے تھے۔ جب تھبہ پر پہنچے تو میری روح فنا ہوگئی۔ یہاں سے لوگ دوپہر کے وقت بھی نہ گزرتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں ایک شہر غرق ہوا تھا۔ مرنے والوں کی روحیں اسی ٹیلے پر رہتی تھیں اور آنے جانے والوں کا کلیجہ چبا جاتی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا تو داؤ جی نے میرے گلے کے گرد مفلر اچھی طرح لپیٹ کر کہا: ”سامنے ان دو کیکروں کے درمیان اپنی پوری رفتار سے دس چکر لگاؤ۔ پھر سو لمبی سانسیں کھینچو اور چھوڑ دو۔ تب میرے پاس آؤ۔ میں یہاں بیٹھتاہوں۔“
میں تھبہ سے جان بچانے کے لیے سیدھا ان کیکروں کی طرف روانہ ہوگیا۔ پہلے ایک بڑے سے ڈھیلے پر بیٹھ کر آرام کیا اور ساتھ ہی حساب لگایا کہ چھ چکروں گا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اونٹ کی طرح کیکروں کے درمیان دوڑنے لگا اور جب دس یعنی چار چکر پورے ہوگئے تو پھر اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ ایک تو درخت پر عجیب و غریب قسم کے جانور بولنے لگے تھے، دوسرے میری پسلی میں بلا کا درد شروع ہوگیا تھا۔ یہی مناسب سمجھا کہ تھبہ پر جاکر داؤ جی کو سوئے ہوئے اٹھاؤں اور گھر لے جاکر خوب خاطر کروں۔ غصہ سے بھرا اور دہشت سے لرزتا میں ٹیلے کے پاس پہنچا۔ داؤ جی تھبہ کی ٹھیکریوں پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنا محبوب شعر گار ہے تھے:
جفا کم کن کہ فردا روزِ محشر
بہ پیشِ عاشقاں شرمندہ باشی!
کبھی دونوں ہتھیلیاں زور سے زمین پر مارتے اور سر اوپر اٹھاکر انگشتِ شہادت فضا میں یوں ہلاتے۔ جیسے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے کہہ رہے ہو دیکھ لو، سوچ لو میں تمہیں…. میں تمہیں بتارہا ہوں …. سنارہا ہوں…. ایک دھمکی دیے جاتے تھے۔ پھر تڑپ کر ٹھیکریوں پر گرتے اور جفا کم کن جفا کم کن کہتے ہوئے رونے لگتے۔ تھوڑی دیر میں ساکت و جامد کھڑا رہا اور پھر زور سے چیخ مار کر بجائے قصبہ کی طرف بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔
داؤ جی ضرور اسمِ اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ بالکل الف لیلیٰ با تصویر والا جن تھا۔ جب داؤ جی کا طلسم اس پر نہ چل سکا تو اس نے انہیں نیچے گرالیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے جفا کم کن جفا کم کن مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ میں اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر رونے لگا…. تھوڑی دیر بعد داؤ جی آئے انہوں نے پہلے جیسا چہرہ بنا کر کہا: ”چل طنبورے“ اور میں ڈرتا ڈرتا ان کے پیچھے ہولیا۔ راستہ میں انہوں نے گلے میں لٹکتی ہوئی کھلی پگڑی کے دونوں کونے ہاتھ میں پکڑ لیے اور جھوم جھوم کر گانے لگے۔
تیرے لمے لمے وال فریدا ٹریا جا!
اس جادو گر کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے واقعی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا سر تبدیل ہوگیا۔ ان کی لمبی لمبی زلفیں کندھوں پر جھولنے لگیں اور ان کا سارا وجود جٹا دھاری ہوگیا…. اس کے بعد چاہے کوئی میری بوٹی بوٹی اڑا دیتا، میں ان کے ساتھ سیرکو ہر گز نہ جاتا!
اس واقعہ کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے کہ ہمارے گھر میں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آکر گرنے لگے۔ بے بے نے آسمان سر پر اٹھالیا۔ کتیا کی بچوں کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئی۔ سچ مچ ان سے لپٹ گئی اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرادیا۔ وہ چلا رہی تھی۔ ”بڈھے ٹوٹکی یہ سب تیرے منتر ہیں۔ یہ سب تیری خارسی ہے۔ تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آگیا ہے۔ تیرے پریت میرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں۔ اجاڑ مانگتے ہیں۔ موت چاہتے ہیں۔“
پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی: ”میں مر گئی، میں جل گئی، لوگوں اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا سمبندھ کیا ہے۔ مجھ پر جادو کیا ہے اور میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔“
امی چند تو داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا اور اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیونکر ہو سکتے تھے لیکن جنوں کی خشت باری انہیں کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بھی بے بے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی بار مجھے جھڑک کر کہا: ”تو احمق ہے اور تیری بے بے ام الجاہلین…. میری ایک سال کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس تو نے مجھے مایوس کردیا۔ اے وائے کہ تو شعور کی بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس…. صد افسوس“
بے بے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراہتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جابیٹھا…. اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر جارہا تھا تو راستے میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کرکے پوچھا: ”بابو تیرے کوئی اینٹ ڈھیلا تو نہیں لگا؟ سنا ہے تمہارے پنڈت کے گھر میں روڑے گرتے ہیں۔“
میں نے اس کمینہ کے منہ لگنا پسند نہ کیا اور چپ چاپ ڈیوڑھی میں داخل ہوگیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پراپوزیشن سنتے ہوئے پوچھنے لگے: ”بیٹا کیا تم سچ مچ جن، بھوت یا پری چڑیل کو کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟“
میں نے اثبات میں جواب دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے واقعی تو بہت بھولا ہے اور میں نے خواہ مخواہ جھڑ ک دیا۔ بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اس طرح سے اینٹیں پھینک سکتے ہیں۔ ہم نے جو دلی اور پھتے مزدور کو بلاکر برساتی بنوائی ہے، وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے لیکن یہ تو بتا کہ جن صرف اینٹیں پھینکنے کا کام ہی کرتے ہیں کہ چنائی بھی کرلیتے ہیں۔“
میں نے جل کر کہا: ”جتنے مذاق چاہو کرلو، مگر جس دن سر پٹھے گا اس دن پتا چلے گا داؤ“۔
داؤ جی نے کہا: ”تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو تا قیامت سر نہیں پھٹ سکتا، اس لیے کہ وہ نہ ہے نہ اس سے اینٹ اٹھائی جاسکے گی اور نہ میرے تیرے یا تیری بے بے کے سر میں لگے گی۔“
پھر بولے: ”سن! علمِ طبعی کا موٹا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لائی جاسکتی…. سمجھ گیا؟“
”سمجھ گیا۔“ میں نے چڑکر کہا۔
ہمارے قصبہ میں ہائی سکول ضرور تھا لیکن میٹرک کا امتحان کا سنٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ صبح آگئی جس دن ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع جارہی تھی اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ہجوم تھا اور اس ہجوم میں داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ اور سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤ ں سے نواز رہے تھے اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کرکے جلدی جلدی سوال پوچھ رہے تھے اور میرے ساتھ ساتھ خود ہی جواب دیتے جاتے تھے۔ اکبر کی اصطلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے، وہاں سے پلٹتے تو ”اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا کہ اپنی وضع سے ہندو معلوم ہوتا تھا۔ وہ نشہ میں چور تھا ایک صاحبِ جمال اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی اور جدھری چاہتی تھی پھراتی تھی“ کہہ کر پوچھتے تھے یہ کون تھا؟
”جہانگیر “ میں نے جواب دیا۔ اور وہ عورت۔ ”نور جہان“ ہم دونوں ایک ساتھ بولے….
”صفتِ مشبہ اور اسم فاعل میں فرق؟“ میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کیں۔ بولے مثالیں؟ میں نے مثالیں دیں۔ سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آگئے اور پوچھنے لگے بریک ان اور بیک ان ٹو کو فقروں میں استعمال کرو۔ ان کا استعمال بھی ہوگیا اور موٹر سٹارٹ ہو چلی تو اس کے ساتھ قدم اٹھاکر بولے: طنبورے مادیاں گھوڑیاں ماکیاں مرغی…. مادیاں گھوڑیاں…. ماکیاں…. ایک سال بعد خدا خدا کرکے یہ آواز دور ہوئی اور میں نے آزادی کا سانس لیا!
پہلے دن تاریخ کا پرچہ بہت اچھا ہوا۔ دوسرے دن جغرافیہ کا اس بھی بڑھ کر، تیسرے دن اتوار تھا اور اس کے بعد حساب کی باری تھی۔ اتوار کی صبح کو داؤ جی کا کوئی بیس صفحہ لمبا خط ملا جس میں الجبرے کے فارمولوں اور حساب کے قاعدوں کے علاوہ اور اور کوئی بات نہ تھی۔
حساب کا پرچہ کرنے کے بعد برآمدے میں میں نے لڑکوں سے جوابات ملائے تو سو میں سے اسی نمبر کا پرچہ ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہوگیا۔ زمین پر پاؤں نہ پڑتا تھا اور میرے منہ سے مسرت کے نعرے نکل رہے تھے۔ جونہی میں نے برآمدے سے پاؤں باہر رکھا، داؤ جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ اور ”اسی نمبر، اسی نمبر“ کے نعرے لگانے شروع کردیے۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر تلخی سے پوچھا: ”کون سا سوال غلط ہوگیا؟“
میں نے جھوم کر کہا: ”چار دیواری والا۔“
جھلاکر بولے: ”تو نے کھڑکیاں اور دروازے منفی نہ کیے ہوں گے۔“ میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جھلاتے ہوئے کہا: ”ہاں ہاں جی…. گولی مارو کھڑکیوں کو۔“
داؤ جی ڈوبی ہوئی آواز میں بولے: ”تو نے مجھے برباد کردیا طنبورے۔ سال کے تین سو پینسٹھ دن میں پکار پکار کر کہتا رہا سطحات کا سوال آنکھیں کھول کر حل کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ بیس نمبر ضائع کیے…. پورے بیس نمبر۔“
اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری اسی فیصد کامیابی بیس فیصد ناکامی کے نیچے یوں دب گئی گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ راستہ بھر وہ اپنے آپ سے کہتے رہے: ”اگر ممتحن اچھے دل کا ہوا تو دو ایک نمبر تو ضرور دے گا، تیرا باقی حل تو ٹھیک ہے“۔
اس پرچے کے بعد داؤ جی امتحان کے آخری دن تک میرے ساتھ رہے۔ وہ رات کے بارہ بجے تک مجھے اس سرائے میں بیٹھ کر پڑھاتے جہاں کلاس مقیم تھی اور اس کے بعد بقول ان کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلے جاتے۔ صبح آٹھ بجے پھر آجاتے اور کمرہ امتحان تک میرے ساتھ چلتے۔
امتحان ختم ہوتے ہی میں نے داؤ جی کو یوں چھوڑ دیا گویا میری ان سے جان پہچان نہ تھی۔ سار ا دن دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا اور شام کو ناولیں پڑھا کرتا۔ اس دوران میں اگر کبھی فرصت ملتی تو داؤ جی کو سلام کرنے بھی چلا جاتا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ہر روز کم از کم ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزاروں تاکہ وہ مجھے کالج کی پڑھائی کے لیے بھی تیار کریں لیکن میں ان کے پھندے میں آنے والا نہ تھا۔ مجھے کالج میں سو بار فیل ہونا گوارا تھا اور ہے لیکن داؤ جی سے پڑھنا منظور نہیں۔ پڑھنے کو چھوڑئیے ان سے باتیں کر نا بھی مشکل تھا۔ میں نے کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ میں نے کچھ جواب دیا فرمایا اس کی ترکیب نحوی کرو۔ حوالداروں کی گائے اندر گھس آئی، میں اسے لکڑی سے باہر نکال رہا ہوں اور داؤ جی پوچھ رہے ہیں cow ناؤن ہے یا ورب۔ اب ہر عقل کا اندھا پانچویں جماعت پڑھا جانتا ہے کہ گائے اسم ہے مگر داؤ جی فرما رہے ہیں کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی۔۔
cow to کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا۔ اور یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب میں امتحان سے فارغ ہوکر نتیجہ کا انتظار کررہا تھا…. پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ہم چند دوست شکار کھیلنے کے لیے نکلے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ منصفی کے آگے سے نہ جائیں کیونکہ وہاں داؤ جی ہوں گے اور مجھے روک کر شکار، بندوق اور کارتوسوں کے محاورے پوچھنے لگیں گے۔ بازار میں دکھائی دیتے تو میں کسی بغلی گلی میں گھس جاتا۔ گھر پر رسماً ملنے جاتا تو بے بے سے زیادہ اور داؤ جی سے کم باتیں کرتا۔ اکثر کہا کرتے: ”افسوس! آفتاب کی طرح تو بھی ہمیں فراموش کررہا ہے۔“ میں شرارتاً خیلے خوب خیلے خوب کہہ کر ہنسنے لگتا۔
جس دن نتیجہ نکلا اور ابا جی لڈوؤں کی چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے، داؤ جی سر جھکائے اپنے حصیر میں بیٹھے تھے۔ ابا جی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر سے کرسی اٹھالیے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے: ”ڈاکٹر صاحب! آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن اسے بھی مقسوم کی خوبی سمجھیے، میراخیال تھاکہ اس کی فرسٹ ڈویژن آجائے گی لیکن اس کی بنیاد کمزور تھی….“
”ایک ہی تو نمبر کم ہے۔“ میں نے چمک کر بات کاٹی۔ اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے: ”تو نہیں جانتا اس ایک نمبر سے میرا دل دو نیم ہوگیا ہے۔ خیر میں اسے منجانب اللہ خیال کرتا ہوں۔“
پھر اباجی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بے بے کے ساتھ گپیں لڑانے میں مشغول ہوگیا۔
اول او ل کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوگیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے سکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو بھی سلام کر آتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے۔ کوٹ، پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے۔ ”اگر مجھے اٹھنے نہیں دیتا تو خود کرسی لے لے“ اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے میں جو کتابیں ساتھ لایا کرتا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آکر کتابیں دیکھ جاتے۔ امی چند بوجوہ کالج چھوڑ کر بنک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بے بے کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ نہ لاتے تھے۔ بی بی کے خط آتے تھے وہ اپنے گھر میں خوش تھی….
کالج کی ایک سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو دو سال پہلے ہمارے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں بنت عم بنت بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ائیر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپو ٹاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دہ اور سہانا بن گیا۔
انہی ایام میں میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا ایک پیکٹ خریدا تھا اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دسہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے ملاقات ہوسکی تھی نہ کرسمس کی تعطیلات میں۔ ایسے ہی ایسٹر گزر گیا اور یوں ہی ایام گزرتے رہے…. ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوالیا۔ ہمارے لیے یہ بہت محفوظ جگہ تھی۔ بنیے ساہو کار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی!
ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور دو ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والے اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگادیا اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دئیے۔ دوپہر کو اماں جی نے مجھے دا ؤجی کی خبر لینے بھیجا تو اس جانی پہنچانی گلی میں عجیب و غریب صورتیں نظر آئیں۔ ہمارے گھر یعنی داؤ جی کے گھر کی ڈیوڑھی میں ایک بیل بندھا تھا اور اس کے پیچھے بوری کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے گھر آکر بتایا کہ داؤ جی اور بے بے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے میرا گلا رندھ گیا۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے داؤ جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں اور لوٹ کر نہ آئیں گے۔ داؤ جی ایسے بے وفا تھے!!!….
کوئی تیسرے روز غروب آفتاب کے بعد جب میں مسجد میں نئے پنا ہ گزینوں کے نام نوٹ کرکے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں سو دو سو آدمیوں کی بھیڑ جمع دیکھی، مہاجر لڑکے لاٹھیاں پکڑے نعرے لگا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو پھاڑ کر مرکز میں گھسنے کی کوشش کی مگر مہاجرین کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر سہم گیا۔ ایک لڑکا کسی بزرگ سے کہہ رہا تھا:
”ساتھ والے گاؤں گیا ہوا تھا جب لوٹا تو اپنے گھر میں گھستا چلا گیا۔“
”کون سے گھر میں؟“ بزرگ نے پوچھا۔
”رہتکی مہاجروں کے گھر میں۔“ لڑکے نے کہا۔
”پھر کیا انہوں نے پکڑلیا۔ دیکھا تو ہندو نکلا۔“
اتنے میں بھیڑ میں سے کسی نے چلا کر کہا: ”اوئے رانو جلد آ اوئے جلدی آ…. تیری سامی…. پنڈت…. تیری سامی۔“
رانو بکریوں کا ریوڑ باڑے کی طرف لے جارہا تھا۔ انہیں روک کر اور ایک لاٹھی والے لڑکے کو ان کے آگے کھڑا کرکے وہ بھیڑ میں گھس گیا۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا جیسے انہوں نے داؤ جی کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ملزم کو دیکھے بغیر اپنے قریبی لوگوں سے کہا:
”یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے…. اسے کچھ مت کہو…. یہ تو…. یہ تو….“ خون میں نہائی ہوئی چند آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نوجوان گنڈاسی تول کر بولا:
”بتاؤں تجھے بھی…. آگیا بڑا حمایتی بن کر…. تیرے ساتھ کچھ ہوا نہیں نا۔“ اور لوگوں نے گالیاں بک کر کہا: ”انصار ہوگا شاید۔“
میں ڈر کر دوسری جانب بھیڑ میں گھس گیا۔ رانو کی قیادت میں اس کے دوست داؤ جی کو گھیرے کھڑے تھے اور رانو داؤ جی کی ٹھوڑی پکڑکر ہلارہا تھا اور پوچھ رہا تھا: ”اب بول بیٹا، اب بول۔“
اور دا ؤجی خاموش کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے پگڑی اتار کر کہا: ”پہلے بودی کاٹو بودی“ اور رانو نے مسواکیں کاٹنے والی درانتی سے داؤ جی کی بودی کاٹ دی۔ وہی لڑکا پھر بولا: ”بلادیں جے؟“ اور رانو نے کہا: ”جانے دو بڈھا ہے، میرے ساتھ بکریاں چرایا کرے گا۔“ پھر اس نے داؤ جی کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا: ”کلمہ پڑھ پنڈتا“ اور دا ؤ جی آہستہ سے بولے: ”کون سا؟“
رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے اور بولا: ”سالے کلمے بھی کوئی پانچ سات ہیں!“
جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھماکر کہا: ”چل بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں۔“
اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدا چل رہا ہو!
”اب فکر نہ کریں۔“ داؤ جی نے سر جھکائے کہا۔ ”یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے اور ایک دن….“
اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آگیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مارکر کہا: ”کیسی بات کرتے ہو منشی جی! یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کرسکتا۔“
”کرے گا، کرے گا…. ڈاکٹر صاحب“ داؤ جی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا: ”آپ خاطر جمع رکھیں۔“
پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے: ”میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔“
اباجی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے اور بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داؤ جی نے پیچھے مڑ کر کہا:
”ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے ابھی بھجوا دیجیے گا۔“
داؤ جی مجھے ادھر ادھر گھماتے اور مختلف درختوں کے نام فارسی میں بتاتے نہر کے اسی پل پر لے گئے جہاں پہلے پہل میرا ان سے تعارف ہوا تھا۔ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کر انہوں نے پگڑی اتار کرگود میں ڈال لی۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کرلیں اور کہا: ”آج سے میں تمہیں پڑھاؤں گا اور اگر جماعت میں اول نہ لاسکا تو فرسٹ ڈویژن ضرور دلوا دوں گا۔ میرے ہر ارادے میں خدا وند تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور اس ہستی نے مجھے اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کیا….“
”مجھ سے پڑھائی نہ ہوگی۔“ میں نے گستاخی سے بات کاٹی۔
”تو او ر کیا ہوگا گولو؟“ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔
میں نے کہا: ”میں بزنس کروں گا، روپیہ کماؤں گا اور اپنی کار لے کر یہاں ضرور آؤں گا، پھر دیکھنا….“
اب کے داؤ جی نے میری بات کاٹی اور بڑی محبت سے کہا: ”خدا ایک چھوڑ تجھے دس کاریں دے لیکن ایک ان پڑھ کی کار میں نہ میں بیٹھوں گا، نہ ڈاکٹر صاحب۔“
میں نے جل کر کہا: ”مجھے کسی کی پروا نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر راضی، میں اپنے یہاں خوش۔“
انہوں نے حیران ہو کر پوچھا: ”میری بھی پرواہ نہیں؟“ میں کچھ کہنے ہی والاتھا کہ وہ دکھی سے ہوگئے اور بار بار پوچھنے لگے:
”میری بھی پرواہ نہیں؟“
”او گولو میری بھی پرواہ نہیں؟“
مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا: ”آپ کی تو ہے مگر….“ مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے اگر اپنے حضرت کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی؟ اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا…. تو …. تو….“
انہوں نے فورا پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہاتھ جوڑ کہنے لگے: ”میں حضور کے دربار کا ایک ادنیٰ کتا۔ میں حضرت مولانا کی خاک پا سے بد تر بندہ ہوکر آقا سے یہ کہتا۔ لعنت کا طوق نہ پہنتا؟ خاندانِ ابو جہل کا خانوادہ اور آقا کی ایک نظر کرم۔ حضرت کا ایک اشارہ۔ حضور نے چنتو کو منشی رام بنادیا۔ لوگ کہتے ہیں منشی جی، میں کہتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کا کفش بردار…. لوگ سمجھتے ہیں….“
داؤ جی کبھی ہاتھ جوڑتے، کبھی سر جھکاتے۔ کبھی انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے اشعار پڑھتے جاتے۔ میں کچھ پریشان سا پشیمان سا، ان کا زانو چھوکر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا: ”داؤ جی! داؤ جی“ اور داؤ جی ”میرے آقا، میرے مولانا، میرے مرشد“ کا وظیفہ کیے جاتے۔
جب جذب کا یہ عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھاکر بولے: ”کیا اچھا موسم ہے، دن بھر دھوپ پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے۔“ پھر وہ پل کی دیوار سے اٹھے اور بولے: ”چلو اب چلیں بازار سے تھوڑا سودا خریدنا ہے۔“
میں جیسا سرکش و بد مزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ منفعل اور خجل ان کے ساتھ لوٹا۔ گھمسے پنساری یعنی دیسو یب یب کے باپ کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضرورت کی چند چیزیں خریدیں اور لفافے گود میں اٹھا کر چل دئیے۔ میں بار بار ان سے لفافے لینے کی کوشش کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ ایک عجیب سی شرم ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانع تھی اوراسی تامل اور جھجک میں ڈوبتا ابھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا۔
وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کرو ں گا اور وہیں پڑھا کروں گا۔ کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی ہمارے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک برمی کین لالٹین بھی رکھی تھی۔
بزنس مین بننا اور پاں پاں کرتی پیکارڈ اُڑائے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انار کلی میں ہمارا دفتر، پتا نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہوچکا ہوتا۔
داؤ جی نے میری زندگی اجیرن کردی، مجھے تباہ کردیا، مجھ پر جینا حرام کردیا۔ سارا دن سکول کی بکواس میں گزرتا اور رات، گرمیوں کی مختصر رات، ان کے سوالات کا جواب دینے۔ کوٹھے پر ان کی کھاٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور وہ مونگ، رسول اور مرالہ کی نہروں کے بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بالکل ٹھیک بتادیا ہے۔ وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ میں نے پھر ٹھیک بتا دیا ہے اور انہوں نے پھر انہی نہروں کو آگے لاکھڑا کیا ہے۔میں جل جاتا اورجھڑک کر کہتا: ”مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتاتا“ تو وہ خاموش ہوجاتے اوردم سادھ لیتے، میں آنکھیں بند کرکے سونے کی کوشش کرتا تو وہ شرمندگی کنکر بن کر پتلیوں میں اتر جاتی۔
میں آہستہ سے کہتا: ”داؤ جی۔“
”ہوں۔“ ایک گھمبیر سی آواز آتی۔
’دداؤ جی کچھ اور پوچھو۔“
داؤ جی نے کہا: ”بہت بے آبرو ہوکر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس کی ترکیب نحوی کرو۔“
میں نے سعادت مندی کے ساتھ کہا: ”جی یہ تو بہت لمبا فقرہ ہے، صبح لکھ کر بتا دوں گا کوئی اور پوچھیے۔“
انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اُٹھائے کہا: ”میرا گولو بہت اچھا ہے۔“
میں نے ذر اسوچ کر کہنا شروع کیا بہت اچھا صفت ہے، حرف ربط مل کر بنا مسند….
اور داؤ جی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہاتھ اٹھاکر بولے: جانِ پدر، تجھے پہلے بھی کہا ہے مسند الیہ پہلے بنایا کر۔
میں نے ترکیبِ نحوی سے جان چھڑانے کے لیے پوچھا: ”آپ مجھے جانِ پدر کیوں کہتے ہیں، جانِ داؤ کیوں نہیں کہتے؟“
”شاباش“ وہ خوش ہوکرکہتے۔ ”ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشاکا۔ ان کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتی۔ جو لوگ دن بدن لکھتے یا بولتے ہیں، سخت غلطی کرتے ہیں، روز بروز کہو یا دن پر دن اسی طرح سے….“
اورجب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیبِ نحوی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں الجھ گیا ہوں تو جمائی لے کر پیار سے کہا ”داؤ جی اب تو نیند آرہی ہے!“
”اور وہ ترکیب نحوی؟“ وہ جھٹ سے پوچھتے۔۔۔
اس کے بعد چاہے میں لاکھ بہانے کرتا، ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا، مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے بیٹھے رہتے، بلکہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھاکر سر پر دھر لیتے۔ چنانچہ کچھ بھی ہوتا۔ ان کے ہر سوال کا خاطر خواہ جواب دینا پڑتا۔
امی چند کالج چلا گیا تو اس کی بیٹھک مجھے مل گئی اور داؤ جی کے دل میں اس کی محبت پر بھی میں نے قبضہ کرلیا۔ اب مجھے داؤ جی بہت اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ان کی باتیں جو اس وقت مجھے بری لگتی تھیں، وہ اب بھی بری لگتی ہیں بلکہ اب پہلے سے بھی کسی قدر زیادہ، شاید اس لیے کہ میں نفسیات کا ایک ہونہار طالب علم ہوں اور داؤ جی پرانے مُلّائی مکتب کے پروردہ تھے۔ سب سے بری عادت ان کی اٹھتے بیٹھتے سوال پوچھتے رہنے کی تھی اور دوسری کھیل کود سے منع کرنے کی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ آدمی پڑھتا رہے پڑھتارہے اور جب اس مدقوق کی موت کا دن قریب آئے تو کتابوں کے ڈھیر پر جان دے دے۔ صحتِ جسمانی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی نسخہ تھا، لمبی سیر اور وہ بھی صبح کی۔ تقریباً سورج نکلنے سے دو گھنٹے پیشتر وہ مجھے بیٹھک میں جگانے آتے اور کندھا ہلاکر کہتے: ”اٹھو گولو موٹا ہوگیا بیٹا۔“
دنیاجہاں کے والدین صبح جگانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا صبح ہوگئی یا سورج نکل آیا مگر وہ ”موٹا ہو گیا“ کہہ کر میری تذلیل کیا کرتے۔ میں منمناتا توچمکار کر کہتے: ”بھدا ہوجائے گا بیٹا تو، گھوڑے پر ضلع کا دورہ کیسا کرے گا!“ اور میں گرم گرم بستر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا: ” داؤ جی خدا کے لیے مجھے صبح نہ جگاؤ، چاہے مجھے قتل کردو، جان سے مار ڈالو۔“
یہ فقرہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ فوراً میرے سر پر لحاف ڈال دیتے اور باہر نکل جاتے۔
بے بے کو ان داؤ جی سے اللہ واسطے کا بیر تھا اور داؤ جی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ سارا دن محلے والیوں کے کپڑے سیا کرتیں اور داؤ جی کو کوسنے دئیے جاتیں۔ ان کی اس زبان درازی پرمجھے بڑا غصہ آتا تھا مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہ ہوسکتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ ناگفتنی گالیوں پر اتر آتیں تو داؤ جی میری بیٹھک میں آجاتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے: ”غیبت کرنا بڑا گناہ ہے لیکن میرا خدا مجھے معاف کرے تیری بے بے بھٹیارن ہے اور اس کی سرائے میں، میں، میری قرۃ العین اور تھوڑا تھوڑا، توبھی، ہم تینوں بڑے عاجز مسافر ہیں۔“
اور واقعی بے بے بھٹیارن سی تھی۔ ان کا رنگ سخت کالا تھا اور دانت بے حد سفید، ماتھا محراب دار اور آنکھیں چنیاں سی۔ چلتی تو ایسی گربہ پائی کے ساتھ جیسے (خدا مجھے معاف کرے) کٹنی کنسوئیاں لیتی پھرتی ہے۔ بچاری بی بی کو ایسی ایسی بری باتیں کہتی کہ وہ دو دو دن رو رو کر ہلکان ہوا کرتی۔ ایک امی چند کے ساتھ اس کی بنتی تھی۔ شاید اس وجہ سے کہ دونوں ہم شکل تھے یا شاید اس وجہ سے کہ اس کو بی بی کی طرح اپنے داؤ جی سے پیار نہ تھا۔
یوں تو بی بی بے چاری بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس سے میری بھی نہ بنتی۔ میں کوٹھے پر بیٹھا سوال نکال رہا ہوں، داؤ جی نیچے بیٹھے ہیں اور بی بی اوپر برساتی سے ایندھن لینے آئی تو ذرا رک کر مجھے دیکھا، پھر منڈیر سے جھانک کر بولی: ”داؤ جی! پڑھ تونہیں رہا، تنکوں کی طرح چارپائیاں بنارہا ہے۔“
میں غصیل بچے کی طرح منہ چڑا کر کہتا: ”تجھے کیا، نہیں پڑھتا، تو کیوں بڑ بڑ کرتی ہے…. آئی بڑی تھانیدارنی۔“
اور داؤ جی نیچے سے ہانک لگاکر کہتے: ”نہ گولو مولو، بہنوں سے جھگڑا نہیں کرتے۔“
اور میں زور سے چلاتا: ”پڑھ رہا ہوں جی، جھوٹ بولتی ہے۔“
داؤ جی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آجاتے اور کاپیوں کے نیچے نیم پوشیدہ چارپائیاں دیکھ کر کہتے: ”قرۃ بیٹا تو اس کو چڑایا نہ کر۔ یہ جن بڑی مشکل سے قابو کیاہے۔ اگر ایک بار بگڑ گیا تو مشکل سے سنبھلے گا۔“
بی بی کہتی: ”کاپی اٹھا کر دیکھ لو داؤ جی، اس کے نیچے ہے وہ چارپائی جس سے کھیل رہا تھا۔“
میں قہر آلود نگاہوں سے بی بی کو دیکھتا اور وہ لکڑیاں اٹھاکر نیچے اتر جاتی۔ پھر داؤ جی سمجھاتے کہ بی بی یہ کچھ تیرے فائدے کے لیے کہتی ہے ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ مجھے بتاتی پھرے۔ فیل ہویا پاس اس کی بلا سے! مگر وہ تیری بھلائی چاہتی ہے، تیری بہتری چاہتی ہے اور داؤ جی کی یہ بات ہر گز سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میری شکایتیں کرنے والی میری بھلائی کیونکر چاہ سکتی تھی!۔
ان دنوں معمول یہ تھا کہ صبح دس بجے سے پہلے داؤ جی کے ہاں سے چل دیتا۔ گھر جاکر ناشتہ کرتا اور پھر سکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا سکول بھیج دیا جاتا اور شام کو سکول بند ہونے پر گھر آکے لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے یہاں آجاتا۔ پھر رات کا کھانا بھی مجھے داؤ جی کے گھر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن ایام میں منصفی بند ہوتی، داؤ جی سکول کے گراؤنڈ میں آکر بیٹھ جاتے اور میرا انتظار کرنے لگتے۔ وہاں سے گھر تک سوالات کی بوچھاڑ رہتی۔ سکول میں جو کچھ پڑھایا گیا ہوتا اس کی تفصیل پوچھتے، پھر مجھے گھر تک چھوڑ کر خود سیر کو چلے جاتے۔
ہمارے قصبہ میں منصفی کا کام مہینے میں دس دن ہوتا تھا اور بیس دن منصف صاحب بہادر کی کچہری ضلع میں رہتی تھی۔ یہ دس دن داؤ جی باقاعدہ کچہری میں گزارتے تھے۔ ایک آدھ عرضی آجاتی تو دو چار روپے کمالیتے ورنہ فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالعہ کا سلسلہ جاری رکھتے۔ بے بے کا کام اچھا تھا۔ اس کی کتربیونت اور محلے والوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ پچھلے چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہوگئی تھی…. ایک دن خلاف معمول داؤ جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ اس وقت کچہری بند ہوگئی تھی اور داؤ جی نانبائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ہولے سے جاکر ان کا بستہ اٹھا لیا اور ان کے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا: ”چلیے، آج میں آپ کو لینے آیا ہوں۔“ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنہ جیب سے نکال کر نانبائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دئیے۔
میں نے شرارت سے ناچ کر کہا: ”گھر چلیے، بے بے کو بتاؤں گا کہ آپ چوری چوری یہاں چائے پیتے ہیں۔“
داؤ جی جیسے شرمندگی ٹالنے کو مسکرائے اور بولے: ”اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور گڑ کی چائے سے تھکن بھی دور ہوجاتی ہے۔ پھر یہ ایک آنہ میں گلاس بھر کے دیتا ہے۔ تم اپنی بے بے سے نہ کہنا، خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کردے گی۔“
پھر انہوں نے خوفزدہ ہوکر کچھ مایوس ہوکر کہا: ”اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے“۔
اس دن مجھے داؤ جی پر رحم آیا۔ میرا جی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگا مگر اس میں میں نے بے بے سے نہ کہنے کا ہی وعدہ کرکے ان کے کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب اس واقعہ کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ بھی کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داؤ جی کے ہاں دودھ، پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگیں، مگر اس رسد سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ ہاں بے بے کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اور اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ شروع کردیا۔
مجھے یاد ہے، ایک صبح میں دودھ سے بھرا تاملوٹ ان کے یہاں لے کرآیا تھا اور بے بے گھر نہ تھی۔ وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ بابا ساون کے جوہڑ میں اشنان کرنے گئی تھی اور گھر میں صرف داؤ جی اور بی بی تھے۔ دودھ دیکھ کر داؤ جی نے کہا ”چلو آج تینو ں چائے پئیں گے۔ میں دکان سے گڑ لے کر آتاہوں، تم پانی چولہے پر رکھو۔“ بی بی نے جلدی سے چولہا سلگایا۔ میں پتیلی میں پانی ڈال کر لایا اور پھر ہم دونوں وہیں چوکے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ داؤ جی گڑ لے کر آگئے تو انہوں نے کہا: ”تم دونوں اپنے اپنے کام پر بیٹھو چائے میں بناتا ہوں۔“ چنانچہ بی بی مشین چلانے لگی اور میں ڈائریکٹ اِن ڈائریکٹ کی مشقیں لکھنے لگا۔ داؤ جی چولہا بھی جھونکتے جاتے تھے اور عادت کے مطابق مجھے بھی اونچے اونچے بتاتے جاتے تھے۔
گلیلیو نے کہا: ”زمین سورج کے گرد گھومتی ہے“۔ گلیلیو نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ نہ لکھ دینا کہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پانی ابل رہا تھا داؤ جی خوش ہورہے تھے۔ اسی خوشی میں جھوم جھوم کر وہ اپنا تازہ بنایا ہوا گیت گا رہے تھے۔ ”او گولو! او گولو! گلیلیو کی بات مت بھولنا، گلیلیو کی بات مت بھولنا۔“ انہوں نے چائے کی پتی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ برتن ابھی تک چولہے پر ہی تھا اورداؤ جی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پانی کی گل بل گل بل کے ساتھ گولو گلیلیو! گولو گلیلیو کیے جارہے تھے۔ میں ہنس رہا تھا اور اپنا کام کیے جارہا تھا۔ بی بی مسکرارہی تھی اورمشین چلائی جاتی تھی اور ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھرمیں بڑے ہی خوش تھے۔ گویا سارے محلے بلکہ سارے قصبہ کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھرمیں اتر آئی ہوں۔۔۔
اتنے میں دروازہ کھلا اور بے بے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا رنگ فق ہوگیا۔ چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے اندر چائے کے چھوٹے چھوٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے پھرتے تھے اور ممنوع کھیل رچانے والا بڈھا موقع پر پگڑا گیا۔ بے بے نے آگے بڑھ کر چولہے کی طرف دیکھا اور داؤجی نے چوکے سے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا: ”چائے ہے!“
بے بے نے ایک دو ہتڑ داؤ جی کی کمر پر مارا اور کہا: ”بڈھے بروہا تجھے لاج نہیں آتی۔ تجھ پر بہار پھرے، تجھے یم سمیٹے، یہ تیرے چائے پینے کے دن ہیں۔ میں بیوہ گھر میں نہ تھی تو تجھے کسی کا ڈر نہ رہا۔ تیرے بھانویں میں کل کی مرتی آج مروں تیرا من راضی ہو۔ تیری آسیں پوری ہوں۔ کس مرن جوگی نے جنا اور کس لیکھ کی ریکھا نے میرے پلے باندھ دیا…. تجھے موت نہیں آتی…. اوں ہوں تجھے کیوں آئے گی۔“
اس فقرے کی گردان کرتے ہوئے بے بے بھیڑنی کی طرح چوکے پر چڑھی، کپڑے سے پتیلی پکڑ کر چولہے سے اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ گرم گرم چائے کے چھپاکے داؤ جی کی پنڈلیوں اور پاؤں پر گرے اور وہ ”اوہ تیرا بھلا ہو جائے۔ او تیرا بھلا ہوجائے۔“ کہتے وہاں سے ایک بچے کی طرح بھاگے اور بیٹھک میں گھس گئے۔ ان کے اس فرار بلکہ اندازِ فرار کو دیکھ کر میں اور بی بی ہنسے بنا نہ رہ سکے اور ہماری ہنسی کی آواز ایک ثانیہ کے لیے چاروں دیواروں سے ٹکرائی۔
میں تو خیر بچ گیا لیکن بے بے نے سیدھے جاکر بی بی کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیخ کر بولی: ”میری سوت بڈھے سے تیرا کیا ناطہ ہے۔ بتا نہیں تو اپنی پران لیتی ہوں۔ تو نے اس کو چائے کی کنجی کیوں دی؟“
بی بی بیچاری پھس پھس رونے لگی تو میں بھی اندر بیٹھک میں کھسک آیا۔ داؤ جی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور اپنے پاؤں سہلارہے تھے۔ پتا نہیں انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے پھرکیوں گدگدی ہوئی کہ میں الماری کے اندر منہ کرکے ہنسنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور بولے: ”شکرِ کردگار کنم کہ گرفتارم بہ مصیبتے نہ کہ معصیتے۔“
تھوڑی دیر رک کر پھر کہا: ”میں اس کے کتوں کا بھی کتا ہوں جس کے سرِ مُطہّر پر مکے کی ایک کم نصیب بڑھیا غلاظت پھینکا کرتی تھی۔“
میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے: ”آقائے نامدار کا ایک ادنیٰ حلقہ بگوش، گرم پانی کے چند چھینٹے پڑنے پر نالہ شیون کرے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ وہ اپنے محبوبﷺ کے طفیل نارِ جہنم سے بچائے۔ خدائے ابراہیمؑ مجھے جرأت عطا کرے، مولائے ایوبؑ مجھے صبر کی نعمت دے۔“
میں نے کہا: ”داؤ جی آقائے نامدار کون؟“
تو داؤ جی کو یہ سن کر ذرا تکلیف ہوئی۔ انہوں نے شفقت سے کہا: ”جان پدر! یوں نہ پوچھا کر۔ میرے استاد، میرے حضرت کی روح کو مجھ سے بیزار نہ کر، وہ میرے آقا بھی تھے، میرے باپ بھی اور میرے استاد بھی، وہ تیرے دادا استاد ہیں…. دادا استاد…“ اور انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آقائے نامدار کا لفظ اور کوتاہ قسمت مجوزہ کی ترکیب میں نے پہلی بار داؤ جی سے سنی۔ یہ واقعہ سنانے میں انہوں نے کنتی ہی دیر لگادی کیونکہ ایک ایک فقرے کے بعد فارسی کے بیشمار نعتیہ اشعار پڑھتے تھے اور بار بار اپنے استاد کی روح کو ثواب پہنچاتے تھے۔“
جب وہ یہ واقعہ بیان کرچکے تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا: ”داؤ جی آپ کو اپنے استاد صاحب اس قدر اچھے کیوں لگتےتھے اور آپ ان کا نام لے کر ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا نوکر کیوں کہتے ہیں؟“
داؤ جی نے مسکرا کر کہا: ”جو طویلے کے ایک خر کو ایسا بنادے کہ لوگ کہیں یہ منشی چنت رام جی ہیں۔ وہ مسیحا نہ ہو، آقا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟“
میں چارپائی کے کونے سے آہستہ آہستہ پھسل کر بسترمیں پہنچ گیا اور چاروں طرف رضائی لپیٹ کر داؤ جی کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکاکر کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی پنڈلیاں سہلاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد ذرا سا ہنستے اور پھر خاموش ہوجاتے….۔
کہنے لگے: ”میں تمہارا کیا تھا اور کیا ہوگیا…. حضرت مولانا کی پہلی آواز کیا تھی! میری طرف سر مبارک اٹھاکر فرمایا، چوپال زادے ہمارے پاس آؤ۔ میں لاٹھی ٹیکتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چھتہ پٹھار اور دیگر دیہات کے لڑکے نیم دائرہ بنائے ان کے سامنے بیٹھے سبق یاد کررہے تھے۔ ایک دربار لگا تھا اور کسی کو آنکھ اوپر اٹھانے کی ہمت نہ تھی…. میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا: بھئی ہم تم کو روز یہاں بکریاں چراتے دیکھتے ہیں۔ انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ کر ہمارے پاس آجایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو…. پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے گنواروں کی طرح کہا چنتو…. مسکرائے…. تھوڑا سا ہنسے بھی…. فرمانے لگے پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے چنتو رام ہوگا…. میں نے سر ہلا دیا…. حضور کے شاگرد کتاب سے نظریں چراکر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا سا کرتہ تھا۔ پائجامہ کی بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا۔ پاؤں میں ادھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگیہ لپیٹا ہوا تھا۔ ”بکریاں میری….“
میں نے بات کاٹ کرپوچھا: ”آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟“
”ہاں ہاں!“ وہ فخر سے بولے۔ ”میں گڈریا تھا اور میرے باپ کی بارہ بکریاں تھیں۔“
حیرانی سے میرا منہ کھلا رہ گیا اور میں نے معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھا: ”اور آپ سکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے؟“ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے: ”جان پدر اس زمانے میں تو شہروں میں بھی سکول نہیں ہوتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے چوہتر برس پہلے کوئی تمہارے ایم بی ہائی سکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا۔ ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے چار حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیج دیتے…. ان کا سارا خاندان زیورِ تعلیم سے آراستہ اور دینی اور دنیوی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے۔ جدِ امجد مہاراجہ کشمیر کے میر منشی۔ گھرمیں علم کے دریا بہتے تھے۔ فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، اقلیدس، حکمت اور علم ہیئت ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کے تبحرِ علمی کی سب داستانیں سنیں۔ شیفتہ اور حکیم مومن خاں مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے اورخود مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی آزردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی….“
مجھے داؤجی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا: ”پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کردیا؟“ ”ہاں“ داؤ جی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ”ان کی باتیں ہی ایسی تھیں۔ ان کی نگاہیں ہی ایسی تھیں جس کی طرف توجہ فرماتے تھے، بندے سے مولاکردیتے تھے۔ مٹی کے ذرے کو اکسیر کی خاصیت دے دیتے تھے…. میں تو ا پنی لاٹھی زمین پر ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے بوریے پر بیٹھو۔ میں نے کہا: جی اٹھارہ برس دھرتی پر بیٹھے گزر گئے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر مسکرا دئیے، اپنے چوبی صندوقچے سے حروف ابجد کا ایک مقوا نکالا اور بولے الف۔ بے۔ بے۔ تے….“ سبحان اللہ کیا آواز تھی۔ کس شفقت سے بو لے تھے۔ کس لہجہ میں فرما رہے تھے الف، بے، پے، ت “
اور داؤ جی ان حرفوں کا ورد کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھوگئے۔
تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا: ”ادھر رہٹ تھا اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا حوض۔“ پھر انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا: ”اور اس طرف مزارعین کے کوٹھے۔ دونوں کے درمیان حضور کا باغیچہ تھا اور سامنے ان کی عظیم الشان حویلی۔ اسی باغیچے میں ان کا مکتب تھا۔ درِ فیض کھلا تھا جس کا جی چاہے آئے، نہ مذہب کی قید نہ ملک کی پابندی….“
میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد با ادب با ملاحظہ قسم کا فقرہ تیار کرکے پوچھا: ”حضرت مولانا کا اسم گرامی شریف کیا تھا؟“ تو پہلے انہوں نے میرا فقرہ ٹھیک کیا اور پھر بولے۔ ”حضرت اسماعیل چشتی فرماتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہیں جانِ جاناں کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی جانِ جاناں کی رعایت سے مظہر جانِ جاناں بھی کہہ دیتے تھے۔“
میں ایسی دلچسپ کہانی سننے کا ابھی اور خواہش مند تھا کہ داؤ جی اچانک رک گئے اور بولے: ”سب سڈی ایری سسٹم کیا تھا؟ ان انگریزوں کا برا ہو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے یا ملکہ وکٹوریہ کا فرمان لے کر، سارے معاملے میں کھنڈت ڈال دیتے ہیں۔“ سوا کے پہاڑے کی طرح میں نے سب سڈی ایری سسٹم کا ڈھانچہ ان کی خدمت میں پیش کردیا۔ پھر انہوں نے میز سے گرائمر کی کتاب اٹھائی اور بولے: ”باہر جاکر دیکھ کے آ کہ تیری بے بے کا غصہ کم ہوا یا نہیں؟“
میں دوات میں پانی ڈالنے کے بہانے باہر گیا تو بے بے کو مشین چلاتے اور بی بی کو چکوا صاف کرتے پایا۔“
داؤ جی کی زندگی میں بے بے والا پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ گھر میں مطلع صاف ہے اور بے بے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے، تو وہ پکار کر کہتے: ”سب ایک ایک شعر سناؤ“ پہلے مجھی سے تقاضا ہوتا اور میں چھوٹتے ہی کہتا:
لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور
تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور
اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے: ”اولین شعر نہ سنوں گا، اردو کا کم سنوں گا اور مسلسل نظم کا ہر گز نہ سنوں گا۔“
بی بی بھی میر ی طرح اکثر اس شعر سے شروع کرتی۔
شنیدم کہ شاپور دم در کشید
چو خسرو بر آتش قلم در کشید
اس پر داؤ جی ایک مرتبہ پھر آرڈر آرڈر پکارتے۔
بی بی قینچی رکھ کر کہتی:
شورے شد و از خوابِ عدم چشم کشوریم
دیدیم کہ باقی ست شبِ فتنہ غنودیم
داؤ جی شاباش تو ضرور کہہ دیتے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے: ”بیٹا یہ شعر تُو کئی مرتبہ سناچکی ہے۔“
پھر وہ بے بے کی طرف دیکھ کر کہتے: ”بھئی آج تمہاری بے بے بھی ایک سنائے گی۔“ مگر بے بے روکھا سا جواب دیتی: ”مجھے نہیں آتے شیر، کبت“۔
اس پر داؤ جی کہتے: ”گھوڑیاں ہی سنادے۔ اپنے بیٹوں کے بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔“
اس پر بے بے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے لیکن وہ مسکرا نہ سکتی اور داؤ جی عین عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔ ان کے درمیان کبھی امی چند اور کبھی میرا نام ٹانک دیتے۔ پھر کہتے: ”میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا۔ برات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور نکاح نامے میں شہادت کے دستخط کروں گا۔
میں دستور کے مطابق شرماکر نگاہیں نیچی کرلیتا تو وہ کہتے: ”پتا نہیں اس ملک کے کسی شہر میں میری چھوٹی بہو پانچویں یا چھٹی جماعت میں پڑھ رہی ہوگی۔ ہفتہ میں ایک دن لڑکیوں کی خانہ داری ہوتی ہے۔ اس نے تو بہت سی چیزیں پکانی سیکھ لی ہو گی۔ پڑھنے میں بھی ہوشیار ہوگی۔ اس بدھو کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مادیاں گھوڑیاں ہوتی ہے یا مرغی۔ وہ تو فر فر سب کچھ سناتی ہوگی۔ میں تو اس کو فارسی پڑھاؤں گا۔ پہلے اس کو خطاطی کی تعلیم دوں گا پھر خطِ شکستہ سکھاؤں گا۔ مستورات کو خطِ شکستہ نہیں آتا۔ میں اپنی بہو کو سکھا دوں گا…. سن گولو! پھر میں تیرے پاس ہی رہوںگا۔ میں اور میری بہو فارسی میں باتیں کریں گے۔ وہ بات بات پر بفرمائید بفرمائید کہے گی اور تو احمقوں کی طرح منہ دیکھا کرے گا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ”خیلے خوب خیلے خوب“ کہتے۔ جانِ پدر چرا ایں قدر زحمت می کشی…. خوب…. یاد دارم…. اور پتا نہیں کیا کیا کچھ کہتے۔ بچارے داؤ جی! چٹائی پر اپنی چھوٹی سی دنیا بساکر اس میں فارسی کے فرمان جاری کیے جاتے….
ایک دن جب چھت پر دھوپ پر بیٹھے ہوئے وہ ایسی ہی دنیا بساچکے تھے تو ہولے سے مجھے کہنے لگے: ”جس طرح خدا نے تجھے ایک نیک سیرت بیوی اور مجھے سعادت مند بہو عطاکی ہے ویسے ہی وہ اپنے فضل سے میرے امی چند کو بھی دے۔“
اس کے خیالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے، یہ سوانگ، یہ مسلم لیگ یہ بیلچہ پارٹیاں مجھے پسند نہیں اور امی چند لاٹھی چلانا گٹکا کھیلنا سیکھ رہا ہے۔ میری تو وہ کب مانے گا۔ ہاں خدائے بزرگ و برتر اس کو ایک نیک مومن سی بیوی دلا دے تو وہ اسے راہِ راست پر لے آئے گی۔“
اس مومن کے لفظ پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اورمیں چپ سا ہوگیا۔ چپ محض اس لیے ہوا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یقیناً ایسی بات نکلے گی جس سے داؤ جی کو بڑا دکھ ہوگا…. میری اور امی چند کی تو خیر باتیں ہی تھیں، لیکن بارہ جنوری کو بی بی کی برات سچ مچ آگئی۔ جیجا جی رام پرتاب کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتاچکے تھے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بارہ تاریخ کی شام کو بی بی وداع ہونے لگی تو گھر بھرمیں کہرام مچ گیا۔ بے بے زار و قطار رو رہی ہے۔ امی چند آنسو بہا رہا ہے اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور باربار کہہ رہے ہیں آج زمین کچھ میرے پاؤ ں نہیں پکڑتی۔ میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے: ”منشی جی اب ہمیں اجازت دیجیے“ تو بی بی پچھاڑ کر گر پڑی۔ اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا: ”یہ کیا ہوا بیٹا۔ اٹھو! یہ تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے۔ اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔“ بی بی اس طرح دھاڑیں مارتے ہوئے داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: ”قرۃ العین میں تیرا گنہگار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا۔ تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کردے گی اور شاید برخوردار رام پرتاب بھی لیکن میں اپنے کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا خجل سر تیرے سامنے خم ہے۔“
یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے کتنے سارے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا: ”منشی جی آپ فکر نہ کریں میں بیٹی کو کریما پڑھا دوں گا۔“ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑکر کہا: ”کریما تو یہ پڑھ چکی ہے، گلستان بوستان بھی ختم کر چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔“ اس پر وہ ہنس کر بولے: ”ساری گلستان تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی، آگے گزر جاتا تھا….“ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے، بی بی نے گوٹہ لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سکھیوں کے بازوؤں میں ڈیوڑھی کی طرف چل دی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر کہا: ”یہ لو یہ بھی رو رہا ہے۔ دیکھو ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ اوگولو…. او مردم دیدہ…. تجھے کیا ہو گیا…. جانِ پدر تو کیوں….“
اس پر ان کا گلا رندھ گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہوگئے۔ برات والے تانگوں اور اِکوں پر سوار تھے۔ بی بی رتھ میں جارہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں اور ہمارے درمیان میں داؤجی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھا تے او ر کہتے: ”لا حول پڑھو بیٹا، لاحول پڑھو۔“ اور خود آنکھوں پر رکھے رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔
رانو ہمارے محلے کا کثیف سا انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھر ی تھی۔ وہ باڑہ جس کا میں نے ذکر کیاہے، اسی کا تھا۔ اس میں بیس تیس بکریاں اور گائیں تھیں جن کا دودھ صبح و شام رانو گلی کے بغلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یونہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو ”پنڈتا جے رام جی کی“ کہہ کر سلام کیا کرتا۔
داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا بھی کہ وہ پنڈت نہیں ہیں معمولی آدمی ہیں کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک بڑے پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ کو چباکر کہتا: ”ارے بھئی جس کے سر پر بودی (چٹیا) ہو وہی پنڈت ہوتا ہے….“
چوروں یاروں سے اس کی آشنائی تھی شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا اور گندی اور فحش بولیوں کا مشاعرہ۔ بی بی کے جانے کے ایک دن بعد جب میں اس سے سے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے آنکھ میچ کر کہا: ”مورنی تو چلی گئی بابو اب تو اس گھر میں رہ کر کیا لے گا؟“ میں چپ رہا تو اس نے جھاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا: ”گھر میں گنگا بہتی تھی سچ بتا کہ غوطہ لگایا کہ نہیں؟“
مجھے اس بات پر غصہ آگیا اور میں نے تاملوٹ گھماکر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضربِ شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہ ہوا لیکن وہ چکراکر تخت پر گرپڑا اور میں بھاگ گیا۔ داؤ جی کو سارا واقعہ سناکر میں دوڑا دوڑا اپنے گھرگیا اور ابا جی سے ساری حکایت بیان کی۔ ان کی بدولت رانو کی تھانہ میں طلبی ہوئی اور حوالدار صاحب نے ہلکی سی گو شمالی کے بعد اسے سخت تنبیہ کرکے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد رانو دا ؤجی پر آتے جاتے طرح طرح کے فقرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا تھا اور واقعی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا اچھی نہ لگتی تھی۔ مگر وہ کہتے تھے: ”یہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز ہے۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کر اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگاکر چمکاتی تھی۔ گو میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے اور جب میں دیال سنگھ میموریل ہائی سکول سے ایک سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا: ”شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟“ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے اور ہم ساخوش قسمت استاد بھی خال خال ہوگا جسے تم ایسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کر فرمانے لگے چنت رام ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے لمس کا کیافائدہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ میں نے کہا اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں۔ میں اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نذر کردوں لیکن میرا بس نہیں چلتا…. خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی سہی۔ تم سلامت رہو کہ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی دس سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا ہے….“ داؤ جی گزرے ایام کی تہہ میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے۔
”میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڑھی میں جا کر آواز دیتا ”خادم آگیا“ مستورات ایک طرف ہو جاتیں تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی طرف بڑھتا۔ پاؤں چھوتا اور پھر حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت فرماتے اور پھر کہتے: ”لو بھئی چنت رام ان گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھالو۔“ میں سبدِ گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آجاتا۔ کبھی فرماتے، ہمیں باغ کا چکر دو کبھی حکم ہوتا سیدھے رہٹ کے پاس لے چلو اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے چنت رام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے، یہی فرماتے رہے کہ کبھی جی چاہتا ہے تو تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میں وضو کرنے والے چبوترے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے دیکھا تھا اس کے بعد جرأت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن میں منہ چھپا لیتا اور پھر اسی وقت سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبے کی لمبی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا۔ تو فرماتے ہم جانتے ہیں چنت رام تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبہ کی سیر کراتے ہو لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا لدا پھرتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہما ہے دوسرے تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں۔ اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطۂ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔
اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی ایک ہماہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کردیا ہے…. جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا، اس قدر خوش ہوئے گویا ہفت اقلیم کی بادشاہی نصیب ہو گئی۔ دین و دنیا کی ہر دعا سے مجھے مالا مال کیا۔ دستِ شفقت میرے سر پر پھیرا اور جیب سے ایک روپیہ نکال کر انعام دیا۔ میں نے اسے حجرِ اسود جان کر بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاکر دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے جو کام ہم سے نہ ہوسکا، وہ تو نے کردکھایا۔ تو نیک ہے خدا نے تجھے یہ سعادت نصیب کی۔ چنت رام تیرا مویشی چرانا پیشہ ہے تُو شاہ بطحا کا پیرو ہے، اس لیے خدائے عز و جل تجھے برکت دیتا ہے وہ تجھے اور بھی برکت دے گا۔ تجھے اور کشائش میسر آئے گی….“
داؤ جی یہ باتیں کرتے کرتے گھٹنوں پر سر رکھ کر خاموش ہوگئے۔
میرا امتحان قریب آرہا تھا اور داؤ جی سخت ہوتے جارہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر فارغ وقت پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا۔ ایک مضمون سے عہدہ برا ہوتا تو دوسرے کی کتابیں نکال کر سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ پانی پینے اٹھتا تو سایہ کی طرح ساتھ ساتھ چلے آتے اور نہیں تو تاریخ کے سن ہی پوچھتے جاتے۔ شام کے وقت سکول پہنچنے کا انہوں نے وطیرہ بنالیا تھا۔ ایک دن میں سکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کی بجائے بورڈنگ کی راہ پر کھسک لیا تو انہوں نے جماعت کے کمرے کے سامنے آکر بیٹھنا شروع کردیا۔ میں چڑچڑا اور ضدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہوگیا تھا۔ ”داؤ جی“ کے بچے، گویا میرا تکیہ کلام بن گیا تھا اور کبھی کبھی جب ان کی یا ان کے سوالات کی سختی بڑھ جاتی تو میں انہیں کتے کہنے سے بھی نہ چوکتا۔ ناراض ہو جاتے تو بس اس قدر کہتے: ”دیکھ لے ڈومنی تو کیسی باتیں کررہاہے۔ تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہی بتاؤں گا کہ جانِ پدر یہ تیرے باپ کو کتا کہتا تھا۔“
میری گالیوں کے بدلے وہ مجھے ڈومنی کہا کرتے تھے۔ اگر انہیں زیادہ دکھ ہوتا تو منہ چڑی ڈومنی کہتے۔ اس سے زیادہ نہ انہیں غصہ آتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا۔ میرے اصلی نام سے انہوں نے کبھی نہیں پکارا۔ میرے بڑے بھائی کا ذکر آتا تو بیٹا آفتاب، برخوردار آفتاب کہہ کر انہیں یاد کرتے تھے لیکن میرے ہر روز نئے نئے نام رکھتے تھے۔ جن میں گولو انہیں بہت مرغوب تھا۔ طنبورا دوسرے درجہ پر، مسٹرہونق اور اخفش اسکوائر ان سب کے بعد آتے تھے اور ڈومنی صرف غصہ کی حالت میں۔ کبھی کبھی میں ان کو بہت دق کرتا۔ وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہان کی ابجد کو ضرب دے دے کر تنگ آچکا ہوں تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے لگتا:
تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نیو دسنا
دا ؤ جی حیرانی سے میری طرف دیکھتے تو میں تالیاں بجانے لگتا اور قوالی شروع کردیتا۔ نیوں نیوں نیوں دسنا۔ تے دکھ تینوں نیوں دسنا…. دسنا دسنا دسنا…. تینوں تینوں تینوں۔ سارے گاما رونا رونا سارے گاما رونا رونا…. تے دیکھ تینوں نیوں دسنا۔ وہ عینک کے اوپر سے مسکراتے۔ میرے پاس آکر کاپی اٹھاتے، صفحہ نکالتے اور تالیوں کے درمیان اپنا بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیتے۔
”سن بیٹا“ وہ بڑی محبت سے کہتے۔ ” یہ کوئی مشکل سوال ہے!“ جونہی وہ سوال سمجھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے میں پھر تالیاں بجانے لگتا۔ ”دیکھ پھر، میں تیرا داؤ نہیں ہو؟“ وہ بڑے مان سے پوچھتے۔
”نہیں“ میں منہ پھاڑ کر کہتا۔
” تو اور کون ہے ؟“ وہ مایوس سے ہو جاتے۔
”وہ سچی سرکار“ میں انگلی آسمان کی طرف کر کے شرارت سے کہتا۔ وہ سچی سرکار، وہ سب کا پالنے والا…. بول بکرے سب کا والی کون؟“
وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے تو میں ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا ”داؤ جی خفا ہوگئے کیا؟“
وہ مسکرانے لگتے۔ ”چھوڑ طنبورے! چھوڑ بیٹا! میں تو پانی پینے جارہا تھا…. مجھے پانی تو پی آنے دے۔
میں جھوٹ موٹ برامان کر کہتا: ”لوجی جب مجھے سوال سمجھنا ہوا داؤ جی کو پانی یاد آگیا۔“
وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور کاپی کھول کر کہتے: ”اخفش اسکوائر جب تجھے چار ایکس کا مربع نظر آرہا تھا تو تو نے تیسرا فارمولا کیوں نہ لگایا اور اگر ایسا نہ بھی کرتا تو….“اور اس کے بعد پتا نہیں داؤ جی کتنے دن پانی نہ پیتے۔
فروری کے دوسرے ہفتہ کی بات ہے۔ امتحان میں کل ڈیڑھ مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کردی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا کُل باون پراپوزیشنیں ہیں زبانی یاد کرلے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں انہیں رٹنے میں مصروف ہوگیا، لیکن جو پراپوزیشن رات کو یاد کرتا، صبح کو بھول جاتا۔
میں دل برداشتہ ہوکر ہمت چھوڑ سی بیٹھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنواکر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہوگئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کرکے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر پھر بیٹھ گیا اور رات کے ڈیڑھ بجے تک لکھ لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگتا تو چند فقروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کرکے اور اپنی حالت کا اندازہ کرکے رونا آگیا اور میں باہر صحن میں آکر سیڑھیوں پر بیٹھ کے سچ مچ رونے لگا۔ گھٹنوں پر سر رکھے رورہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوڑھی کا دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ جب یہ فیصلہ کرچکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑھے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو سسکیوں کا لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔
داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا: ”لے بھئی طنبورے میں تو یوں نہ سمجھتا تھا تو تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔“
پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے آئے۔ بستر میں بٹھاکر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں اوپر کرکے کرسی پر بیٹھ گئے۔
انہوں نے کہا: ”اقلیدس چیز ہی ایسی ہے۔ تو اس کے ہاتھوں یوں نالاں ہے۔ میں اس سے اور طرح تنگ ہوا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر و مقابلہ اور اقلیدس کی جس قدر کتابیں تھیں، انہیں میں اچھی طرح پڑھ کر اپنی کاپیوں پر اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہوگیا ہوں لیکن ایک رات میں اپنی کھاٹ پر پڑا متساوی الساقلین کے ایک مسئلہ پر غور کررہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلاکر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کی رو سے اس کاجواب ٹھیک آتا تھا لیکن علمِ ہندسہ سے پایۂ ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا لیکن تیری طرح سے رویا نہیں۔
علی الصبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دستِ مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی طبعِ رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے: ”چنت رام اب ہم تم کو نہیں پڑھاسکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہوجائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔“
میں نے جرأت کرکے کہہ دیا کہ حضور اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکمِ ربانی سے کم نہیں۔ اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقائے غزنوی کے سامنے ایاز کی مجال! لیکن حضور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ فرمانے لگے: ”تم بے حد جذباتی آدمی ہو۔ بات تو سن لی ہوتی۔“ میں نے سر جھکاکر کہا ارشاد! فرمایا: ”دلی میں حکیم ناصر علی سیستانی علمِ ہندسہ کے بڑے ماہر ہیں۔ اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتسابِ علم کرو۔ ہم ان کے نام رقعہ لکھ دیں گے۔“ میں نے رضا مندی ظاہر کی تو فرمایا اپنی والدہ سے پوچھ لینا اگر وہ رضامند ہوں تو ہمارے پاس آنا…. والدہ مرحومہ سے پوچھا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی۔ چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔
حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ ”گھر کی لپائی تپائی کررہا ہوں۔ جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔“
چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس شکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لا ینحل مسئلہ سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا لیکن حضور سے اجازت مل سکتی تھی نہ رقعہ، وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے اور والدہ اس بڑھاپا میں کیسے آمادہ ہوسکتی تھیں….
ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اورمیں تیری طرح پریشان تھا تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی دو روپے چرائے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے! واقعی میں نے بڑا گناہ کیا اور ابد تک میرا سر ان دونوں کرمفرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا…. گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کی مسند کے پاس پہنچا جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہوکرمیں نے زمین کو بوسہ دیا اور دل میں کہا: ”بدقسمت ہوں، بے اجازت جارہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آکے قدموں میں جان دے دوں گا۔“
اتنا کہہ کر اٹھا اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر میں وہاں سے چل دیا…. ”سن رہا ہے؟“ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔
رضائی کے بیچ خارپشت بنے، میں نے آنکھیں جھپکائیں اور ہولے سے کہا: ”جی!“
داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا: ”قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسہ حصار والی پٹڑی بن رہی تھی۔ یہی راستہ سیدھا دلی کو جاتا تھا اور یہیں مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرتا اور ایک دن چلتا، اس طرح تائیدِ غیبی کے سہارے سولہ دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آگئی تھی لیکن گوہرِ مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حکیم ناصر علی سیستانی کا دولت خانہ کہاں ہے، نفی میں جواب ملتا۔ دو دن ان کی تلاش جاری رہی لیکن پتا نہ پاسکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی۔ انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھیں۔ وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہوکر حکیم صاحب کا پتا معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پھینک کر گہری نیند سوجاتا۔ مثل مشہور ہے جویندہ یابندہ! آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہوگئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلہ کی ایک تیرہ و تاریک گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں فروکش تھے اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہورہی تھی۔ میں جوتے اتارکر دہلیز کے اندر کھڑا ہوگیا۔ ایک صاحب نے پوچھا: ”کون ہے؟“ میں نے سلام کرکے کہا۔ ”حکیم صاحب سے ملنا ہے۔“
حکیم صاحب دوستوں کے حلقہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بولے: ”اسم گرامی؟“ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ”پنجاب سے آیا ہوں اور….“ میں بات پوری بھی نہ کرپایا تھا کہ زور سے بولے: ”اوہو! چنت رام ہو؟“ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے: ”مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنت رام تمہارے پاس آئے۔ ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہوگیا ہے، اس کی مدد کرنا۔“
میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹ دار آواز میں بولے: ”میاں! اندر آجاؤ، کیا چپ کا روزہ رکھا ہے؟“
میں ذرا آگے بڑھا تو بھی میری طرف نہ دیکھا اور ویسے ہی عروسِ نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے تحکمانہ انداز میں کہا: ”برخوردار بیٹھ جاؤ۔“
میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا: ”بھئی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے دو دو ہاتھ کرلینے دو۔“ پھر حکم ہوا ”بتاؤ ہندسہ کا کونسا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟“
میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ آہستہ کُرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہوگئی۔ پھر فرمایا: ”بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر ایک متساوی الساقین۔“
مجھ پر سکتہ کا عالم طاری تھا۔ نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحہ کے بعد بولے: ”میاں جلدی کرو۔ نابینا ہوں۔ کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔“ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر ہانپتی ہوئی انگلیوں سے متساوی الساقین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مرئی شکل بن چکی تو بولے اب اس نقطہ ”س“ سے خط ”ب ج“پر عمود گراؤ۔“
ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا دوسرے وہاں کچھ نہ آتا تھا۔ یونہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے ”ہے ہے کیا کرتے ہو یہ نقطہ ہے کیا؟“
پھر خود ہی بولے ”آہستہ آہستہ عادی ہوجاؤ گے۔“ وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیر متساوی الساقین بن کر ان کی کمر پر ابھر آئیں گی۔
پھر داؤ جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے بے چین ہوکر پوچھا: ”پھر کیا ہوا داؤ جی؟“ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا: ”رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا پھر بتاؤں گا۔“
میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑگیا تو انہوں نے کہا: ”پہلے وعدہ کر کہ آیندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پراپوزیشنوں کو پتاشے سمجھے گا۔“
میں نے جواب دیا: ”حلوہ سمجھوں گا آپ فکر نہ کریں۔“
انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا: ”بس مختصر یہ کہ میں ایک سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحرِعلم سے چند قطرے حاصل کرکے اپنی کور آنکھوں کو دھویا۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فرمانے لگے: چنت رام اگر ہم میں قوت ہو تو ان پاؤں کوکھینچ لیں۔ اس پر میں رو دیا تو دستِ مبارک محبت سے میرے سر پر پھیرکر کہنے لگے: ”ہم تم سے ناراض نہیں ہیں لیکن ایک سال کی فرقت بہت طویل ہے۔ آیندہ کہیں جانا ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔“ یہ کہتے ہوئے داؤ جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ مجھے اسی طرح گم سم چھوڑ کر بیٹھک میں چلے گئے۔“
امتحان کی قربت سے میرا خون خشک ہورہا تھا، لیکن جسم پھول رہا تھا۔ داؤ جی کو میرے موٹاپے کی فکر رہنے لگی۔ اکثر میرے تھن متھنے ہاتھ پکڑ کر کہتے: ”اسپِ تازی بن طویلہ خر نہ بن۔“ مجھے ان کا یہ فقرہ بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجاً ان سے کلام بند کردیتا۔ میرے مسلسل مرن برت نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا اور ان کی فکر، اندیشہ کی حد تک بڑھ گئی۔ ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے آجگایا اور میری منتوں، خوشامدوں، گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کوٹ پہناکر کھڑا کردیا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گویاگھسیٹتے ہوئے باہر گئے۔ سردیوں کی صبح کوئی چار بجے کا عمل۔ گلی میں آدم نہ آدم زاد، تاریکی سے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا اور داؤ جی مجھے اسی طرح سیر کو لے جارہے تھے۔ میں کچھ بک رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ابھی گراں خوابی دور نہیں ہوئی ابھی طنبورا بڑبڑا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد کہتے کوئی سر نکال طنبورے کی آہنگ پر بجا یہ کیا کر رہا ہے!
جب ہم بستی سے دور نکل گئے اور صبح کی یخ ہوا نے میری آنکھوں کو زبردستی کھول دیا تو داؤ جی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ سرداروں کا رہٹ آیا اور نکل گیا۔ ندی آئی اور پیچھے رہ گئی۔ قبرستان گزر گیا مگر داؤ جی تھے کہ کچھ آیتیں ہی پڑھتے چلے جارہے تھے۔ جب تھبہ پر پہنچے تو میری روح فنا ہوگئی۔ یہاں سے لوگ دوپہر کے وقت بھی نہ گزرتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں ایک شہر غرق ہوا تھا۔ مرنے والوں کی روحیں اسی ٹیلے پر رہتی تھیں اور آنے جانے والوں کا کلیجہ چبا جاتی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا تو داؤ جی نے میرے گلے کے گرد مفلر اچھی طرح لپیٹ کر کہا: ”سامنے ان دو کیکروں کے درمیان اپنی پوری رفتار سے دس چکر لگاؤ۔ پھر سو لمبی سانسیں کھینچو اور چھوڑ دو۔ تب میرے پاس آؤ۔ میں یہاں بیٹھتاہوں۔“
میں تھبہ سے جان بچانے کے لیے سیدھا ان کیکروں کی طرف روانہ ہوگیا۔ پہلے ایک بڑے سے ڈھیلے پر بیٹھ کر آرام کیا اور ساتھ ہی حساب لگایا کہ چھ چکروں گا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اونٹ کی طرح کیکروں کے درمیان دوڑنے لگا اور جب دس یعنی چار چکر پورے ہوگئے تو پھر اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ ایک تو درخت پر عجیب و غریب قسم کے جانور بولنے لگے تھے، دوسرے میری پسلی میں بلا کا درد شروع ہوگیا تھا۔ یہی مناسب سمجھا کہ تھبہ پر جاکر داؤ جی کو سوئے ہوئے اٹھاؤں اور گھر لے جاکر خوب خاطر کروں۔ غصہ سے بھرا اور دہشت سے لرزتا میں ٹیلے کے پاس پہنچا۔ داؤ جی تھبہ کی ٹھیکریوں پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنا محبوب شعر گار ہے تھے:
جفا کم کن کہ فردا روزِ محشر
بہ پیشِ عاشقاں شرمندہ باشی!
کبھی دونوں ہتھیلیاں زور سے زمین پر مارتے اور سر اوپر اٹھاکر انگشتِ شہادت فضا میں یوں ہلاتے۔ جیسے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے کہہ رہے ہو دیکھ لو، سوچ لو میں تمہیں…. میں تمہیں بتارہا ہوں …. سنارہا ہوں…. ایک دھمکی دیے جاتے تھے۔ پھر تڑپ کر ٹھیکریوں پر گرتے اور جفا کم کن جفا کم کن کہتے ہوئے رونے لگتے۔ تھوڑی دیر میں ساکت و جامد کھڑا رہا اور پھر زور سے چیخ مار کر بجائے قصبہ کی طرف بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔
داؤ جی ضرور اسمِ اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ بالکل الف لیلیٰ با تصویر والا جن تھا۔ جب داؤ جی کا طلسم اس پر نہ چل سکا تو اس نے انہیں نیچے گرالیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے جفا کم کن جفا کم کن مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ میں اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر رونے لگا…. تھوڑی دیر بعد داؤ جی آئے انہوں نے پہلے جیسا چہرہ بنا کر کہا: ”چل طنبورے“ اور میں ڈرتا ڈرتا ان کے پیچھے ہولیا۔ راستہ میں انہوں نے گلے میں لٹکتی ہوئی کھلی پگڑی کے دونوں کونے ہاتھ میں پکڑ لیے اور جھوم جھوم کر گانے لگے۔
تیرے لمے لمے وال فریدا ٹریا جا!
اس جادو گر کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے واقعی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا سر تبدیل ہوگیا۔ ان کی لمبی لمبی زلفیں کندھوں پر جھولنے لگیں اور ان کا سارا وجود جٹا دھاری ہوگیا…. اس کے بعد چاہے کوئی میری بوٹی بوٹی اڑا دیتا، میں ان کے ساتھ سیرکو ہر گز نہ جاتا!
اس واقعہ کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے کہ ہمارے گھر میں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آکر گرنے لگے۔ بے بے نے آسمان سر پر اٹھالیا۔ کتیا کی بچوں کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئی۔ سچ مچ ان سے لپٹ گئی اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرادیا۔ وہ چلا رہی تھی۔ ”بڈھے ٹوٹکی یہ سب تیرے منتر ہیں۔ یہ سب تیری خارسی ہے۔ تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آگیا ہے۔ تیرے پریت میرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں۔ اجاڑ مانگتے ہیں۔ موت چاہتے ہیں۔“
پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی: ”میں مر گئی، میں جل گئی، لوگوں اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا سمبندھ کیا ہے۔ مجھ پر جادو کیا ہے اور میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔“
امی چند تو داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا اور اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیونکر ہو سکتے تھے لیکن جنوں کی خشت باری انہیں کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بھی بے بے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی بار مجھے جھڑک کر کہا: ”تو احمق ہے اور تیری بے بے ام الجاہلین…. میری ایک سال کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس تو نے مجھے مایوس کردیا۔ اے وائے کہ تو شعور کی بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس…. صد افسوس“
بے بے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراہتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جابیٹھا…. اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر جارہا تھا تو راستے میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کرکے پوچھا: ”بابو تیرے کوئی اینٹ ڈھیلا تو نہیں لگا؟ سنا ہے تمہارے پنڈت کے گھر میں روڑے گرتے ہیں۔“
میں نے اس کمینہ کے منہ لگنا پسند نہ کیا اور چپ چاپ ڈیوڑھی میں داخل ہوگیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پراپوزیشن سنتے ہوئے پوچھنے لگے: ”بیٹا کیا تم سچ مچ جن، بھوت یا پری چڑیل کو کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟“
میں نے اثبات میں جواب دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے واقعی تو بہت بھولا ہے اور میں نے خواہ مخواہ جھڑ ک دیا۔ بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اس طرح سے اینٹیں پھینک سکتے ہیں۔ ہم نے جو دلی اور پھتے مزدور کو بلاکر برساتی بنوائی ہے، وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے لیکن یہ تو بتا کہ جن صرف اینٹیں پھینکنے کا کام ہی کرتے ہیں کہ چنائی بھی کرلیتے ہیں۔“
میں نے جل کر کہا: ”جتنے مذاق چاہو کرلو، مگر جس دن سر پٹھے گا اس دن پتا چلے گا داؤ“۔
داؤ جی نے کہا: ”تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو تا قیامت سر نہیں پھٹ سکتا، اس لیے کہ وہ نہ ہے نہ اس سے اینٹ اٹھائی جاسکے گی اور نہ میرے تیرے یا تیری بے بے کے سر میں لگے گی۔“
پھر بولے: ”سن! علمِ طبعی کا موٹا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لائی جاسکتی…. سمجھ گیا؟“
”سمجھ گیا۔“ میں نے چڑکر کہا۔
ہمارے قصبہ میں ہائی سکول ضرور تھا لیکن میٹرک کا امتحان کا سنٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ صبح آگئی جس دن ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع جارہی تھی اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ہجوم تھا اور اس ہجوم میں داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ اور سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤ ں سے نواز رہے تھے اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کرکے جلدی جلدی سوال پوچھ رہے تھے اور میرے ساتھ ساتھ خود ہی جواب دیتے جاتے تھے۔ اکبر کی اصطلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے، وہاں سے پلٹتے تو ”اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا کہ اپنی وضع سے ہندو معلوم ہوتا تھا۔ وہ نشہ میں چور تھا ایک صاحبِ جمال اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی اور جدھری چاہتی تھی پھراتی تھی“ کہہ کر پوچھتے تھے یہ کون تھا؟
”جہانگیر “ میں نے جواب دیا۔ اور وہ عورت۔ ”نور جہان“ ہم دونوں ایک ساتھ بولے….
”صفتِ مشبہ اور اسم فاعل میں فرق؟“ میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کیں۔ بولے مثالیں؟ میں نے مثالیں دیں۔ سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آگئے اور پوچھنے لگے بریک ان اور بیک ان ٹو کو فقروں میں استعمال کرو۔ ان کا استعمال بھی ہوگیا اور موٹر سٹارٹ ہو چلی تو اس کے ساتھ قدم اٹھاکر بولے: طنبورے مادیاں گھوڑیاں ماکیاں مرغی…. مادیاں گھوڑیاں…. ماکیاں…. ایک سال بعد خدا خدا کرکے یہ آواز دور ہوئی اور میں نے آزادی کا سانس لیا!
پہلے دن تاریخ کا پرچہ بہت اچھا ہوا۔ دوسرے دن جغرافیہ کا اس بھی بڑھ کر، تیسرے دن اتوار تھا اور اس کے بعد حساب کی باری تھی۔ اتوار کی صبح کو داؤ جی کا کوئی بیس صفحہ لمبا خط ملا جس میں الجبرے کے فارمولوں اور حساب کے قاعدوں کے علاوہ اور اور کوئی بات نہ تھی۔
حساب کا پرچہ کرنے کے بعد برآمدے میں میں نے لڑکوں سے جوابات ملائے تو سو میں سے اسی نمبر کا پرچہ ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہوگیا۔ زمین پر پاؤں نہ پڑتا تھا اور میرے منہ سے مسرت کے نعرے نکل رہے تھے۔ جونہی میں نے برآمدے سے پاؤں باہر رکھا، داؤ جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ اور ”اسی نمبر، اسی نمبر“ کے نعرے لگانے شروع کردیے۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر تلخی سے پوچھا: ”کون سا سوال غلط ہوگیا؟“
میں نے جھوم کر کہا: ”چار دیواری والا۔“
جھلاکر بولے: ”تو نے کھڑکیاں اور دروازے منفی نہ کیے ہوں گے۔“ میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جھلاتے ہوئے کہا: ”ہاں ہاں جی…. گولی مارو کھڑکیوں کو۔“
داؤ جی ڈوبی ہوئی آواز میں بولے: ”تو نے مجھے برباد کردیا طنبورے۔ سال کے تین سو پینسٹھ دن میں پکار پکار کر کہتا رہا سطحات کا سوال آنکھیں کھول کر حل کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ بیس نمبر ضائع کیے…. پورے بیس نمبر۔“
اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری اسی فیصد کامیابی بیس فیصد ناکامی کے نیچے یوں دب گئی گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ راستہ بھر وہ اپنے آپ سے کہتے رہے: ”اگر ممتحن اچھے دل کا ہوا تو دو ایک نمبر تو ضرور دے گا، تیرا باقی حل تو ٹھیک ہے“۔
اس پرچے کے بعد داؤ جی امتحان کے آخری دن تک میرے ساتھ رہے۔ وہ رات کے بارہ بجے تک مجھے اس سرائے میں بیٹھ کر پڑھاتے جہاں کلاس مقیم تھی اور اس کے بعد بقول ان کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلے جاتے۔ صبح آٹھ بجے پھر آجاتے اور کمرہ امتحان تک میرے ساتھ چلتے۔
امتحان ختم ہوتے ہی میں نے داؤ جی کو یوں چھوڑ دیا گویا میری ان سے جان پہچان نہ تھی۔ سار ا دن دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا اور شام کو ناولیں پڑھا کرتا۔ اس دوران میں اگر کبھی فرصت ملتی تو داؤ جی کو سلام کرنے بھی چلا جاتا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ہر روز کم از کم ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزاروں تاکہ وہ مجھے کالج کی پڑھائی کے لیے بھی تیار کریں لیکن میں ان کے پھندے میں آنے والا نہ تھا۔ مجھے کالج میں سو بار فیل ہونا گوارا تھا اور ہے لیکن داؤ جی سے پڑھنا منظور نہیں۔ پڑھنے کو چھوڑئیے ان سے باتیں کر نا بھی مشکل تھا۔ میں نے کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ میں نے کچھ جواب دیا فرمایا اس کی ترکیب نحوی کرو۔ حوالداروں کی گائے اندر گھس آئی، میں اسے لکڑی سے باہر نکال رہا ہوں اور داؤ جی پوچھ رہے ہیں cow ناؤن ہے یا ورب۔ اب ہر عقل کا اندھا پانچویں جماعت پڑھا جانتا ہے کہ گائے اسم ہے مگر داؤ جی فرما رہے ہیں کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی۔۔
cow to کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا۔ اور یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب میں امتحان سے فارغ ہوکر نتیجہ کا انتظار کررہا تھا…. پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ہم چند دوست شکار کھیلنے کے لیے نکلے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ منصفی کے آگے سے نہ جائیں کیونکہ وہاں داؤ جی ہوں گے اور مجھے روک کر شکار، بندوق اور کارتوسوں کے محاورے پوچھنے لگیں گے۔ بازار میں دکھائی دیتے تو میں کسی بغلی گلی میں گھس جاتا۔ گھر پر رسماً ملنے جاتا تو بے بے سے زیادہ اور داؤ جی سے کم باتیں کرتا۔ اکثر کہا کرتے: ”افسوس! آفتاب کی طرح تو بھی ہمیں فراموش کررہا ہے۔“ میں شرارتاً خیلے خوب خیلے خوب کہہ کر ہنسنے لگتا۔
جس دن نتیجہ نکلا اور ابا جی لڈوؤں کی چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے، داؤ جی سر جھکائے اپنے حصیر میں بیٹھے تھے۔ ابا جی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر سے کرسی اٹھالیے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے: ”ڈاکٹر صاحب! آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن اسے بھی مقسوم کی خوبی سمجھیے، میراخیال تھاکہ اس کی فرسٹ ڈویژن آجائے گی لیکن اس کی بنیاد کمزور تھی….“
”ایک ہی تو نمبر کم ہے۔“ میں نے چمک کر بات کاٹی۔ اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے: ”تو نہیں جانتا اس ایک نمبر سے میرا دل دو نیم ہوگیا ہے۔ خیر میں اسے منجانب اللہ خیال کرتا ہوں۔“
پھر اباجی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بے بے کے ساتھ گپیں لڑانے میں مشغول ہوگیا۔
اول او ل کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوگیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے سکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو بھی سلام کر آتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے۔ کوٹ، پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے۔ ”اگر مجھے اٹھنے نہیں دیتا تو خود کرسی لے لے“ اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے میں جو کتابیں ساتھ لایا کرتا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آکر کتابیں دیکھ جاتے۔ امی چند بوجوہ کالج چھوڑ کر بنک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بے بے کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ نہ لاتے تھے۔ بی بی کے خط آتے تھے وہ اپنے گھر میں خوش تھی….
کالج کی ایک سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو دو سال پہلے ہمارے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں بنت عم بنت بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ائیر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپو ٹاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دہ اور سہانا بن گیا۔
انہی ایام میں میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا ایک پیکٹ خریدا تھا اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دسہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے ملاقات ہوسکی تھی نہ کرسمس کی تعطیلات میں۔ ایسے ہی ایسٹر گزر گیا اور یوں ہی ایام گزرتے رہے…. ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوالیا۔ ہمارے لیے یہ بہت محفوظ جگہ تھی۔ بنیے ساہو کار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی!
ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور دو ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والے اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگادیا اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دئیے۔ دوپہر کو اماں جی نے مجھے دا ؤجی کی خبر لینے بھیجا تو اس جانی پہنچانی گلی میں عجیب و غریب صورتیں نظر آئیں۔ ہمارے گھر یعنی داؤ جی کے گھر کی ڈیوڑھی میں ایک بیل بندھا تھا اور اس کے پیچھے بوری کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے گھر آکر بتایا کہ داؤ جی اور بے بے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے میرا گلا رندھ گیا۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے داؤ جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں اور لوٹ کر نہ آئیں گے۔ داؤ جی ایسے بے وفا تھے!!!….
کوئی تیسرے روز غروب آفتاب کے بعد جب میں مسجد میں نئے پنا ہ گزینوں کے نام نوٹ کرکے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں سو دو سو آدمیوں کی بھیڑ جمع دیکھی، مہاجر لڑکے لاٹھیاں پکڑے نعرے لگا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو پھاڑ کر مرکز میں گھسنے کی کوشش کی مگر مہاجرین کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر سہم گیا۔ ایک لڑکا کسی بزرگ سے کہہ رہا تھا:
”ساتھ والے گاؤں گیا ہوا تھا جب لوٹا تو اپنے گھر میں گھستا چلا گیا۔“
”کون سے گھر میں؟“ بزرگ نے پوچھا۔
”رہتکی مہاجروں کے گھر میں۔“ لڑکے نے کہا۔
”پھر کیا انہوں نے پکڑلیا۔ دیکھا تو ہندو نکلا۔“
اتنے میں بھیڑ میں سے کسی نے چلا کر کہا: ”اوئے رانو جلد آ اوئے جلدی آ…. تیری سامی…. پنڈت…. تیری سامی۔“
رانو بکریوں کا ریوڑ باڑے کی طرف لے جارہا تھا۔ انہیں روک کر اور ایک لاٹھی والے لڑکے کو ان کے آگے کھڑا کرکے وہ بھیڑ میں گھس گیا۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا جیسے انہوں نے داؤ جی کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ملزم کو دیکھے بغیر اپنے قریبی لوگوں سے کہا:
”یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے…. اسے کچھ مت کہو…. یہ تو…. یہ تو….“ خون میں نہائی ہوئی چند آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نوجوان گنڈاسی تول کر بولا:
”بتاؤں تجھے بھی…. آگیا بڑا حمایتی بن کر…. تیرے ساتھ کچھ ہوا نہیں نا۔“ اور لوگوں نے گالیاں بک کر کہا: ”انصار ہوگا شاید۔“
میں ڈر کر دوسری جانب بھیڑ میں گھس گیا۔ رانو کی قیادت میں اس کے دوست داؤ جی کو گھیرے کھڑے تھے اور رانو داؤ جی کی ٹھوڑی پکڑکر ہلارہا تھا اور پوچھ رہا تھا: ”اب بول بیٹا، اب بول۔“
اور دا ؤجی خاموش کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے پگڑی اتار کر کہا: ”پہلے بودی کاٹو بودی“ اور رانو نے مسواکیں کاٹنے والی درانتی سے داؤ جی کی بودی کاٹ دی۔ وہی لڑکا پھر بولا: ”بلادیں جے؟“ اور رانو نے کہا: ”جانے دو بڈھا ہے، میرے ساتھ بکریاں چرایا کرے گا۔“ پھر اس نے داؤ جی کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا: ”کلمہ پڑھ پنڈتا“ اور دا ؤ جی آہستہ سے بولے: ”کون سا؟“
رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے اور بولا: ”سالے کلمے بھی کوئی پانچ سات ہیں!“
جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھماکر کہا: ”چل بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں۔“
اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدا چل رہا ہو!